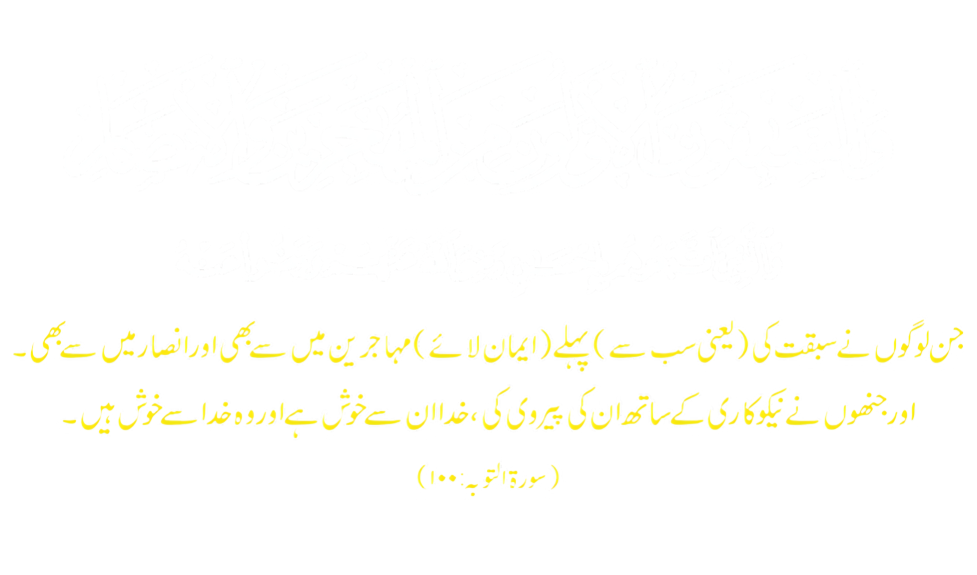روافض کی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر دروغ گوئی گنہگار کون ہے؟ عقیدہ اہلِ سنت پر رافضی الزام و شبہ کا رد
امام ابن تیمیہاشکال
شیعہ مصنف لکھتا ہے: ’’ایک وہ تقسیم ہے جو ہمارے سید و مولیٰ امام موسیٰ بن جعفر کاظم رحمہ اللہ سے وارد ہے آپ صغیر السن تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان سے دریافت کیا، معصیت (نافرمانی، گناہ) کس سے صادر ہوتی ہے؟ امام موسیٰ نے جواباً فرمایا:
1۔ بندے سے
2۔ اللہ تعالیٰ سے
3۔ یا دونوں سے
اگر معصیت کا مصدر و منبع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ بندے پر کیوں کر ظلم کر سکتا ہے، اور اسے ناکردہ گناہ کی سزا کیونکر دے سکتا ہے؟ اور اگر دونوں سے صادر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اور بندہ گناہ کے ارتکاب میں برابر کے شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ قوی ہے اور اس لائق ہے کہ اپنے ضعیف بندے سے منصفانہ برتاؤ کرے گا اور اگر بندہ گناہ کا مرتکب ہونے میں منفرد ہے تو مذمت و ملامت کا سزاوار بھی وہی ہو گا، اور ثواب و عقاب کا زیادہ مستحق بھی وہی ہو گا اور اسی کے لیے جنت یا جہنم واجب ہو گی۔ اس پر امام ابو حنیفہؒ نے یہ آیت پڑھی:
ذُرِّيَّةً بَعۡضُهَا مِنۡ بَعۡضٍ۞(سورۃ آل عمران: آیت، 34)
ترجمہ: ’’ایسی نسل جس کا بعض بعض سے ہے۔‘‘
(انتہیٰ کلام الرافضی)
جواب: اس سے کہا جائے گا کہ جو بات سنداً مذکور ہو ہم اسکی صحت سے آگاہ ہیں، جو بات شیعہ مصنف نے بیان کی ہے وہ قطعی طور پر جھوٹ ہے اس واقعہ کی کوئی قابلِ ذکر صحیح اور معروف اسناد نہیں پائی جاتی کیونکہ منقولات کی صحت جاننے کا مدار ان کی اسناد ثابتہ ہوتی ہیں۔ بالخصوص جب کسی باب میں کذب کی کثرت بھی ہو اور جب کسی واقعہ کا کذب ظاہر و باطن ہو تب تو اشکال ہی نہیں رہتا، کیونکہ جو لوگ امام صاحب اور ان کے مذہب سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہؒ تقدیر کے قائل ہیں اور انہوں نے ’’فقہ اکبر‘‘ (کتاب فقہ اکبر کے بارے میں بعض کم علم لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ امام ابو حنیفہؒ کی تالیف نہیں، بلکہ کسی اور ابو حنیفہ نامی آدمی نے لکھ کر امام صاحب کی طرف منسوب کر دی ہے۔ یہ بات ان کبار و قدیم علماء کے اقوال کے مخالف ہے جو اسے امام ابو حنیفہؒ کی تالیف لطیف تسلیم کرتے ہیں جیسے استاذ ابو منصور عبدالقاہر بغدادیؒ، فخر الاسلام علی البزدویؒ، و دیگر حضرات یہ امام شیخ الاسلام ابنِ تیمیہ رحمہ اللہ ہیں، جنہیں کتابوں کا ایک جامع احاطہ حاصل ہے آپ بھی اسی چیز کی صراحت کرتے ہیں جس کی صراحت متقدمین علماء نے کی ہے۔ حالانکہ استاذ ابو منصور رحمہ اللہ شافعی ہیں اور فخر الاسلام رحمہ اللہ حنفی اور ابنِ تیمیہ رحمہ اللہ حنبلی ہیں۔ استاذ ابو منصورؒ اپنی کتاب ’’التبصرۃ ‘‘میں فرماتے ہیں: ’’فقہاء میں سے سب سے پہلے جس ہستی نے معتزلہ کے عقائد کا بطلان ثابت کیا وہ حنفیہ کے امام امام ابو حنیفہؒ ہیں۔'‘
میں منکرین تقدیر کی تردید کی ہے اس کتاب میں امام صاحب نے جس تفصیل کے ساتھ قدریہ کا رد کیا ہے کسی اور کا نہیں کیا اور امام صاحب کے متبعین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ہی امام صاحب کا مذہب ہے اور یہی حنفیہ کا بھی مذہب ہے۔ اب فروع میں امام صاحب کی طرف کوئی شخص معتزلہ کے بارے میں امام صاحب کی بابت ایسی کوئی حکایت نقل نہیں کر سکتا۔ بلکہ یہ معتزلہ اور قدریہ آئمہ احناف کے نزدیک ان کا قول مفتی بہ ہوتا ہے۔ مذموم، معیوب، بدعتی اور اہل زیغ و ضلال ہیں۔ لہٰذا امام صاحب اس شخص کی تائید نہیں کر سکتے، جو یہ کہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے افعال کو پیدا نہیں کیا مزید برآں امام موسیٰ بن جعفرؒ متقدمین شیعہ اور دیگر علماء اہلِ بیت تقدیر کے قائل تھے انکار تقدیر شیعہ میں اس وقت رائج ہوا جب وہ بنوبویہ (بنوبویہ نے ایران اور بلادِ مشرق کو تشیع کے جہنم میں جھونک دیا، یہ شیعہ کا پہلا دور تھا، دوسرے دور کا آغاز خدا بندہ نامی سلطان کے عہدِ حکومت سے ہوتا ہے، اسی بادشاہ کے لیے اس شیعہ مصنف نے یہ کتاب تصنیف کی جس کی تردید کے لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کو قلم اٹھانا پڑا، شیعہ کا تیسرا دور ایران کے سلاطین صفویہ سے شروع ہوتا ہے۔) کے دور حکومت میں معتزلہ سے مل جل گئے، اس عقیدہ کا ان سے منقول ہونا ظاہر اور معروف ہے جبکہ خود قدماء شیعہ قدر و صفات کے اثبات پر متفق تھے بعد میں ان لوگوں میں قدریہ آ ملے تھے۔
شیعہ مصنف نے امام موسیٰ بن جعفرؒ سے جو قول نقل کیا ہے اس کے بیان کرنے والے زیادہ تر منکرین تقدیر کے کم سن لوگ اور بچے ہیں، یہ نظریہ قدریہ کے آغازِ ظہور اور امام موسیٰ کی ولادت سے بھی پہلے لوگوں میں معروف تھا کیونکہ موسیٰ بن جعفرؒ مدینہ میں 128ھ یا 129ھ میں دولت عباسیہ سے تقریباً تین برس پہلے پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے بغداد میں 183ھ میں وفات پائی تھی۔ ابو حاتم کہتے ہیں: موسیٰ بن جعفرؒ ثقہ، صدوق اور آئمہ مسلمین میں سے ہیں اور قدریہ اس تاریخ سے قبل پیدا ہوئے ہیں یہ امر محتاجِ بیان نہیں کہ قدریہ نے اموی دور میں حضرت عبداللہ بن زبیرؓ اور عبدالملک بن مروانؒ کے عہدِ خلافت میں پرزے نکالنے شروع کئے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حکایت سراپا کذب ہے کیونکہ امام ابو حنیفہؒ جن سے ملے تھے وہ جعفر بن محمدؒ ہیں، رہے موسیٰ بن جعفرؒ تو وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے کہ جن سے امام ابو حنیفہؒ سوال پوچھتے، اور نہ ان کے ساتھ کہیں جمع ہوئے۔ امام صاحب کے اقران و معاصرین میں سے تو جعفر بن محمدؒ تھے اور ابو حنیفہؒ بایں علمی شہرت کے ان سے علم لینے والے نہ تھے تب پھر بھلا وہ موسیٰ بن جعفرؒ سے کیونکر علم حاصل کرتے؟
پھر رافضی نے اس حکایت میں جو یہ قول نقل کیا ہے کہ ’’اللہ اس بات سے کہیں زیادہ عدل والا ہے کہ وہ اپنے بندے پر ظلم کرے اور اس کے نا کردہ پر اس کا مؤاخذہ کرے۔‘‘ کہ یہ قدریہ کے کلام کی اصل و اساس ہے جسے عوام و خواص سب جانتے ہیں۔ یہ ان کے مذہب کی اساس اور ان کا شعار ہے۔ اسی لیے یہ لوگ خود کو ’’عدلیہ‘‘ بھی کہلاتے ہیں۔ لہٰذا اگر تو اس حکایت کی موسیٰ بن جعفرؒ کی طرف نسبت درست ہے تو اس میں ان کی نہ کوئی فضیلت ہے اور نہ تعریف و مدح جبکہ قدریہ کے بچے بھی اس کو جانتے ہیں پھر اس وقت حال ہو گا جب یہ حکایت جھوٹی اور اختلافی ہو؟
دوسرا جواب: اس تقسیم کی بابت یہ ہے کہ یہ تقسیم حصری نہیں کیونکہ قائل کا یہ قول کہ:
"اَلْمَعْصِیَۃُ مِمَّنْ" ایک مجمل و مبہم لفظ ہے جو محتاجِ تشریح ہے۔ ظاہر ہے کہ معصیت ہو یا اطاعت و عبادت وہ ایک عرض (وہ چیز جو اپنے وجود میں کسی دوسری چیز کی محتاج ہو) ہے جو قائم بالغیر ہے اور ضروری طور پر اپنے قیام میں کسی محل کی محتاج ہے اور لامحالہ یہ بات بھی پوشیدہ نہیں کہ اس کا قیام بندے کے ساتھ ہے اللہ کے ساتھ نہیں، اور جو چیز بھی اللہ کی پیدا کردہ ہے اس کے متعلق یہ کہنا درست ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، بایں معنیٰ کہ وہ اس کی پیدا کردہ ہے، مگر یہ الگ چیز ہے یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ قائم ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے موصوف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:
وَسَخَّرَ لَـكُمۡ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الۡاَرۡضِ جَمِيۡعًا مِّنۡهُ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوۡمٍ يَّتَفَكَّرُوۡنَ ۞(سورۃ الجاثية: آیت، 13)
ترجمہ: اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے ان سب کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیں۔
دوسری جگہ ارشاد فرمایا:
وَمَا بِكُمۡ مِّنۡ نّـِعۡمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ۞(سورۃ النحل: آیت، 53)
ترجمہ: ’’تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔‘‘
اب اگرچہ رب تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اسی نے خیر و شر کو پیدا کیا ہے اور اس میں اس اعتبار سے حکمت ہے کہ اسکا فعل حسن اور متفق ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے:
الَّذِىۡۤ اَحۡسَنَ كُلَّ شَىۡءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلۡقَ الۡاِنۡسَانِ مِنۡ طِيۡنٍ ۞(سورۃ السجدة: آیت، 7)
ترجمہ: جس نے اچھا بنایا ہر چیز کو جو اس نے پیدا کی اور انسان کی پیدائش تھوڑی سی مٹی سے شروع کی۔‘‘
اور فرمایا:
صُنۡعَ اللّٰهِ الَّذِىۡۤ اَتۡقَنَ كُلَّ شَىۡءٍ۞(سورة النمل: آیت، 88)
ترجمہ: ’’اس اللہ کی کاری گری سے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا۔‘‘
اس لیے نرے شر کی اللہ کی طرف نسبت نہ کی جائے گی بلکہ یا تو اسے عموم میں داخل کر کے ذکر کریں گے یا سبب کی طرف مضاف کریں گے یا اس کے فاعل کو محذوف کر کے ذکر کریں گے۔ پہلی کی مثال: ارشاد ربانی ہے:
اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىۡءٍ۞(سورۃ: الزمر آیت، 62)
ترجمہ: ’’اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔‘‘
دوسری کی مثال:
قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ الۡفَلَقِ ۞مِنۡ شَرِّ مَا خَلَقَ۞(سورة الفلق: آیت، 1،2)
ترجمہ: ’’تو کہہ میں مخلوق کے رب کی پناہ پکڑتا ہوں۔ اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔‘‘
تیسری کی مثال وہ ہے جو جن کی حکایت کے تحت ہے۔ارشاد ہے:
وَّاَنَّا لَا نَدۡرِىۡۤ اَشَرٌّ اُرِيۡدَ بِمَنۡ فِى الۡاَرۡضِ اَمۡ اَرَادَ بِهِمۡ رَبُّهُمۡ رَشَدًا ۞(سورۃ الجن: آیت، 10)
ترجمہ: ’’اور یہ کہ بے شک ہم نہیں جانتے کیا ان لوگوں کے ساتھ جو زمین میں ہیں، کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔‘‘
اور سورۂ فاتحہ میں ارشاد ہے:
اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَـقِيْمَ ۞صِرَاطَ الَّذِيۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا الضَّآلِّيۡنَ۞ (سورۃ الفاتحۃ: آیت، 5، 6)
ترجمہ: ’’ہمیں سیدھے راستے پر چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں۔‘‘
پس اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ فاعل نعمت ہے جبکہ فاعل غضب کو حذف کر دیا اور ضلالت کو ان کی طرف منسوب فرمایا اور حضرت ابراہیم (خلیل) علیہ السلام فرماتے ہیں:
وَاِذَا مَرِضۡتُ فَهُوَ يَشۡفِيۡنِ ۞(سورة الشعراء: آیت، 80)
ترجمہ:’’اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔‘‘
اس لیے جملہ اسمائے حسنیٰ اللہ ہی کے ہیں رب تعالیٰ نے اپنے وہ اسمائے حتیٰ رکھے ہیں جو سراسر خیر کو ہی مقتضی ہیں اور شر کو صرف مفعولات میں ذکر کیا جائے گا۔ جیسا کہ ارشاد ہے:
اِعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيۡدُ الۡعِقَابِ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ ۞
(سورۃ المائدہ: آیت، 98)
ترجمہ: ’’جان لو! بیشک اللہ بہت سخت عذاب والا ہے اور بیشک اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔‘‘
اور سورة انعام کے آخر میں ارشاد ہے
اِنَّ رَبَّكَ سَرِيۡعُ الۡعِقَابِ وَ اِنَّهٗ لَـغَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ ۞(سورة الانعام: آیت، 165)
ترجمہ: ’’بے شک تیرا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک و بے حد بخشنے والا مہربان ہے۔‘‘
اور سورة الاعراف میں ارشاد ہے:
اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيۡعُ الۡعِقَابِ وَاِنَّهٗ لَـغَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ ۞(سورة الاعراف: آیت، 167)
ترجمہ: ’’بے شک تیرا رب یقیناً بہت جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بے حد بخشنے والا رحم والا ہے۔‘‘
اور فرمایا:
نَبِّئۡ عِبَادِىۡۤ اَنِّىۡۤ اَنَا الۡغَفُوۡرُ الرَّحِيۡمُ۞وَاَنَّ عَذَابِىۡ هُوَ الۡعَذَابُ الۡاَلِيۡمُ ۞(سورة الحجر: آیت، 49، 50)
ترجمہ: میرے بندوں کو خبر دے دے کہ بے شک میں ہی بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہوں۔ اور یہ بھی کہ بے شک میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔‘‘
اور فرمایا:
حٰمٓ۞ تَنۡزِيۡلُ الۡكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الۡعَزِيۡزِ الۡعَلِيۡمِ ۞غَافِرِ الذَّنۡبِ وَقَابِلِ التَّوۡبِ شَدِيۡدِ الۡعِقَابِ ذِى الطَّوۡلِ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِلَيۡهِ الۡمَصِيۡرُ ۞(سورة غافر: آیت، 1تا3)
ترجمہ: ’’حٓمٓ اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے، جو سب پر غالب، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، بہت سخت سزا والا، بڑے فضل والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔‘‘
یہ اس لیے کہ وہ امور جن میں بعض بندوں کے اعتبار سے شر ہوتا ہے رب تعالیٰ کی ان کے پیدا کرنے میں ایک حکمت ہوتی ہے وہ ان کو پیدا کر کے بھی حمید و مجید ہے اسی کی بادشاہی اور اسی کی تعریف ہے اور اس کی طرف نسبت کے اعتبار سے یہ امور شر نہیں ہیں اور نہ مذموم ہی ہیں سو اس کی طرف ایسی کسی بات کی نسبت نہ کی جائے گی جو اس کی نقیض سمجھی جائے۔ جیسا کہ رب تعالیٰ بیماریوں، تکلیفوں، ناگوار ہواؤں، بدبوؤں، بدصورتوں، خبیث اجسام وغیرہ کا خالق ہے جیسے سانپ، بچھو، غلاظتیں اور نجاستیں وغیرہ کیونکہ اس کی اس میں زبردست حکمت ہے۔
پس جب یہ کہا جائے گا کہ یہ ناگوار ہوائیں اور گندگیاں اللہ کی طرف سے ہیں وہ اس بات کا وہم ڈالتا ہے کہ شاید یہ ناگوار بدبوئیں اللہ سے نکلی ہیں حالانکہ اللہ اس بات سے برَی ہے۔ اسی طرح جب یہ کہا جائے گا کہ قبائح یا معاصی اللہ کی طرف سے ہیں کہ اس سے کبھی اس بات کا وہم ہوتا ہے کہ یہ باتیں اللہ کی ذات سے نکلی ہیں جیسا کہ بندے کی ذات سے نکلتے ہیں جیسا کہ متکلم کی ذات سے کلام نکلتا ہے حالانکہ اللہ کی ذات اس سے منزہ ہے یا اس سے اس بات کا وہم ہوتا ہے کہ یہ گندی چیزیں اس سے قبیح اور بَری ہیں۔ حالانکہ وہ اس سے بَری ہے بلکہ تفویض اور تعلیل دونوں اقوال کی رو سے رب تعالیٰ کی ہر آفرینش حسن ہی حسن ہے اسی طرح ذائقوں، رنگوں اور بوؤں کے بارے میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ میٹھا یا کڑوا ذائقہ اللہ کی طرف سے ہے یا اس بوٹی سے ہے یا یہ اچھی یا بری بو اللہ کی طرف سے ہے یا فلاں عین سے ہے اس طرح کی اور بھی متعدد مثالیں ہیں اور کبھی جب یہ کہا جائے گا کہ ’’یہ اللہ کی طرف سے ہے،‘‘ تو اس بات کا بھی وہم ہوتا ہے کہ شاید اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ حالانکہ نہ تو فحش بات کاحکم دیتا ہے اور نہ فساد کو پسند کرتا ہے اور نہ ہی اپنے بندوں سے کفر پر راضی ہوتا ہے۔‘‘
یہ حضرتِ ابن مسعودؓ کے اس قول کے مثل ہے جب ان سے مفوضہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپؓ نے فرمایا: ’’میں ان کے بارے میں اپنی رائے سے کہوں گا۔ اگر تو یہ رائے درست ہوئی تو اللہ کی طرف سے ہو گی اور اگر یہ رائے خطا ہو گی تو میرے اور شیطان کی طرف سے ہو گی اور اللہ اور اس کا رسول اللہﷺ دونوں اس سے بَری ہوں گے۔‘‘
اسی طرح حضرت ابوبکر صدیقؓ نے بھی علامہ کے بارے میں کہا تھا اور ایسا ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی کہا تھا۔
ان لوگوں کی مراد یہ تھی کہ درستگی کا کبھی رب تعالیٰ نے امر کیا ہوتا ہے، اور اسے مشروع کیا ہوتا ہے اور اسے پسند ہوتی ہے اور وہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ جبکہ شر کا نہ تو اس نے امر دیا ہوتا ہے، نہ اسے محبوب ہوتی ہے اور نہ اس نےخطا کو مشروع کیا ہوتا ہے بلکہ یہ تزیینِ نفس اور تزیینِ شیطان سے ہوتی ہے جو بندہ شیطان کے امر سے کرتا ہے یہی مطلب ہے اسبات کا کہ وہ مجھ سے اور شیطان سے ہو گی۔ تب بھی اس کے متعدد جوابات ہیں:
اول: یہ کہا جائے کہ اعمال، اقوال، طاعات اور معاصی سب بندے سے ہیں بایں معنیٰ کہ وہ بندے کے ساتھ قائم ہیں اور اس کی قدرت و مشیت سے حاصل ہیں وہ ان سے متصف بھی ہے اور متحرک بھی، جن کا حکم اس کی طرف لوٹتا ہے کیونکہ بسا اوقات محل کے ساتھ متصف شے کے بارے میں یہ بھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ اس محل سے نکلی ہے چاہے اس کو اس کا اختیار نہ بھی ہو جیسا کہ کہتے ہیں: یہ ہوا فلاں خطے کی ہے، یہ پھل فلاں درخت کا ہے، یہ غلہ فلاں کھیت کا ہے، تو جو کسی زندہ بااختیار سے صادر ہو، اسے بدرجہ اول یہ کہنا جائز ہوگا کہ یہ شے فلاں سے ہے اور وہ اللہ سے ہے، بایں معنیٰ کہ اس نے اسے پیدا کیا ہے اس حال میں کہ وہ اس کے غیر سے قائم ہے اور اس نے ان چیزوں کو بندے کا عمل، کسب اور صفت ٹھہرایا ہے۔
اس نے ان کو اپنی مشیت اور قدرت سے اس بات کے واسطے سے پیدا کیا ہے کہ اس نے بندے کی قدرت و مشیت کو پیدا کیا جیسا کہ وہ مسببات کو ان کے اسباب کے ذریعے پیدا کرتا ہے۔ پس وہ بادلوں کو ہواؤں سے، اور بارش کو بادلوں سے اور نباتات کو بارش سے پیدا کرتا ہے۔
حوادث کی ان کے خالق کی طرف نسبت ایک اعتبار سے ہوتی ہے۔ جبکہ ان کے اسباب کی طرف نسبت ایک دوسرے اعتبار سے ہوتی ہے۔ پس یہ اللہ کی طرف سے اس اعتبار سے ہیں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہیں جو اس کے غیر میں پیدا کی گئی ہیں اور جیسا کہ مخلوقات کی جملہ حرکات و صفات اس سے ہیں جبکہ بندے اس کی صفتِ قائمہ ہونے کے اعتبار سے ہیں۔ جیسا کہ حرکت کا صدور اس متحرک سے ہوتا ہے جو اس حرکت سے متصف ہو چاہے وہ جماد ہی ہو۔ پس اس وقت کیا ہو گا جب وہ متحرک حیوان ہو؟
تب بھی اضافت کی جہت کے مختلف ہونے کی وجہ سے بندے اور رب کے درمیان کوئی شرکت نہیں۔ جیسا کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں عورت سے ہے تو یہ اس اعتبار سے ہے کہ اس عورت نے اسے جنا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ اس اعتبار سے ہے کہ اسے اللہ نے پیدا کیا ہے کہ دونوں نسبتوں میں کوئی تناقض نہیں۔ لہٰذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پھل درخت کا ہے اور یہ غلہ کھیت کا ہے تو یہ بایں معنیٰ ہوتا ہے کہ ان کا اس میں حدوث ہوا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے بایں معنیٰ ہوتا ہے کہ اس نے اس پھل اور کھیتی کو پیدا کیا ہے کہ ان دونوں باتوں میں کوئی تناقض نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:
اَمۡ خُلِقُوۡا مِنۡ غَيۡرِ شَىۡءٍ اَمۡ هُمُ الۡخٰلِقُوۡنَ ۞
ترجمہ: ’’یا وہ کسی چیز کے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں، یا وہ (خود) پیدا کرنے والے ہیں؟‘‘
اس کی مشہور تفسیر ’’ام خلقو من غیر رب‘‘ ہے۔ جبکہ ایک تفسیر ’’ام خلقوا من غیر عنصر‘‘ بھی ہے۔
اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جب ایک قبطی مارا گیا تو انہوں نے یہ کہا تھا:
هٰذَا مِنۡ عَمَلِ الشَّيۡطٰنِ ۞( سورۃ القصص: آیت، 15)
’’کہا یہ شیطان کے کام سے ہے۔‘‘
اور فرمایا:
مَاۤ اَصَابَكَ مِنۡ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَاۤ اَصَابَكَ مِنۡ سَيِّئَةٍ فَمِنۡ نَّـفۡسِكَ۞(سورۃ النساء: آیت، 79)
ترجمہ: ’’جو بھلائی تجھے پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو برائی تجھے پہنچے وہ تیرے نفس کی طرف سے ۔‘‘
اسی کے ساتھ اس سے قبل یہ ارشاد بھی پڑھیے:
قُلۡ كُلٌّ مِّنۡ عِنۡدِ اللّٰهِ۞(سورۃ النساء: آیت، 78)
ترجمہ: کہہ دے سب اللہ کی طرف سے ہے۔
سو یہاں پرحسنات و سئیات سے مراد نعمتیں اور مصائب ہیں۔ اسی لیے فرمایا:
’’مَآ اَصَابَکَ‘‘ اور یہ نہیں فرمایا کہ "مااصبت"
جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:
اِنۡ تَمۡسَسۡكُمۡ حَسَنَةٌ تَسُؤۡهُمۡ وَاِنۡ تُصِبۡكُمۡ سَيِّئَةٌ يَّفۡرَحُوۡا بِهَا۞ (سورۃ آل عمران: آیت، 120)
ترجمہ: ’’اگر تمھیں کوئی بھلائی پہنچے تو انھیں بری لگتی ہے اور اگر تمھیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں ۔‘‘
اور فرمان الہٰی ہے:
اِنۡ تُصِبۡكَ حَسَنَةٌ تَسُؤۡهُمۡ وَاِنۡ تُصِبۡكَ مُصِيۡبَةٌ يَّقُوۡلُوۡا قَدۡ اَخَذۡنَاۤ اَمۡرَنَا مِنۡ قَبۡلُ وَيَتَوَلَّوْا وَّهُمۡ فَرِحُوۡنَ ۞(سورة التوبة: آیت، 50)
ترجمہ: ’اگر تجھے کوئی بھلائی پہنچے تو انھیں بری لگتی ہے اور اگر تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں ہم نے تو پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا اور اس حال میں پھرتے ہیں کہ وہ بہت خوش ہوتے ہیں ۔‘‘
رب تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ نعمتیں اور مصائب اس کی طرف سے ہیں ۔ پس نعمت تو ابتداء سے ہی اللہ کی طرف سے ہے جبکہ مصیبت نفسِ انسانی سے کسی سبب سے ہوتی ہے اور وہ اس کے گناہ ہیں۔ جیسا کہ ایک دوسری آیت ارشادہے:
وَمَاۤ اَصَابَكُمۡ مِّنۡ مُّصِيۡبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتۡ اَيۡدِيۡكُمۡ وَيَعۡفُوۡا عَنۡ كَثِيۡرٍ ۞(سورۃ الشورى: آیت، 30)
ترجمہ: ’’اور جو بھی تمھیں کوئی مصیبت پہنچی تو وہ اس کی وجہ سے ہے جو تمھارے ہاتھوں نے کمایا اور وہ بہت سی چیزوں سے در گزر کر جاتا ہے۔‘‘
ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:
اَوَلَمَّاۤ اَصَابَتۡكُمۡ مُّصِيۡبَةٌ قَدۡ اَصَبۡتُمۡ مِّثۡلَيۡهَا قُلۡتُمۡ اَنّٰى هٰذَا قُلۡ هُوَ مِنۡ عِنۡدِ اَنۡفُسِكُمۡ ۞(سورۃ آل عمران: آیت، 165)
ترجمہ: ’’اور کیا جب تمھیں ایک مصیبت پہنچی کہ یقیناً اس سے دگنی تم پہنچا چکے تھے تو تم نے کہا یہ کیسے ہوا؟ کہہ دے یہ تمھاری اپنی طرف سے ہے۔‘‘
وہ اس لیے کہ وہ محسنِ عدل ہے۔ اس سے ملنے والی ہر نعمت اس کا فضل ہے اور اس کی ہر نعمت اس کا عدل ہے اور وہ بندے پر اس کی طرف سے بنا کسی سبب کے فضل و احسان کر کے محسن ہے۔ جبکہ بدون گناہ کے وہ عقاب نہیں کرتا۔ اگرچہ اس نے ان سب افعال کو اپنی حکمت کے تحت پیدا کیا ہے۔ بے شک وہ حکیم عادل ہے اشیاء کو ان کے مواقع پر رکھتا ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا۔
پھر جب غیر خدا اپنے نوکر کو اس کی زیادتی پر سزا دے سکتا ہے، چاہے وہ اس بات کا مقر بھی ہو کہ بندوں کے افعال کا خالق اللہ ہے اور یہ اس کی طرف سے ظلم بھی نہیں مقصود ہوتا۔ تو رب تعالیٰ اس بات کا بدرجہ اولیٰ مستحق ہے کہ گناہ پر سزا دینے میں وہ ظالم نہ ہو تو جب انسان ایک مقتضائے حکمت مصلحت کو کر سکتا ہے جو کسی حیوان کو تعذیب دیے بغیر حاصل نہ ہوتی ہو (جیسے جانور کو گوشت کھانے کے لیے ذبح کرنا) اور وہ ایسا کر کے بھی ظالم نہ کہلائے تو ایسی تعذیب رب تعالیٰ سے بدرجہ اولیٰ ظلم نہ ہو گی۔
دوم: یہ کہا جائے کہ یہ افعال اللہ کی طرف سے بایں معنیٰ ہیں کہ اس نے ان کو اپنے غیر میں پیدا کیا ہے اور انہیں اپنے غیر کا فعل قرار دیا ہے اور یہ بندے کی طرف سے بایں معنیٰ ہیں کہ یہ اس کا فعل اس کی ذات کے ساتھ قائم اور اس کا کسب ہیں جن کے ذریعے وہ جلبِ منفعت اور دفعِ مضرت کا کام لیتا ہے اور بندے کا یہ اعتبار کہ وہ فعل اس کے ساتھ قائم ہے اور اس کے ضرر و انتفاع کا حکم خاص اسی کی طرف لوٹتا ہے کہ یہ ایسا اعتبار ہے جو اللہ کے شایانِ شان نہیں۔ کیونکہ بندوں کے افعال رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہوتے اور نہ وہ ان افعال سے متصف ہوتا ہے اور نہ ان کے وہ احکام ہی اس کی طرف لوٹتے ہیں جو اپنے موصوفات کی طرف لوٹتے ہیں۔
رب تعالیٰ کا یہ اعتبار کہ اس نے ان افعال کو پیدا کیا اور ان کو اپنے غیر کا، ان میں قدرت، مشیت اور فعل کو پیدا کر کے فعل بنایا ہے، ایسا اعتبار ہے جو بندہ کے لائق نہیں کہ ان باتوں پر سوائے اللہ کے کسی کو قدرت نہیں۔ اس لیے اکثر مثبتین قدر کا قول ہے: کہ بندے کے افعال رب تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور بندے کا فعل ہیں۔
جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا فعل ہیں تو مراد اللہ کا مفعول ہونا ہوتا ہے نا یہ کہ یہ وہ فعل ہے جو مصدر کا مسمی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خلق اور مخلوق میں فرق کرتے ہیں یہ اکثر آئمہ کا قول ہے اور یہ قاضی ابو یعلیٰؒ کے دو اقوال میں سے آخری قول ہے اور یہی امام احمدؒ کے اکثر اصحاب کا قول ہے اور یہی قاضی ابو یعلیٰؒ کے دو بیٹوں قاضی ابوحازمؒ اور قاضی ابو الحسینؒ وغیرہ کا قول ہے۔
سوم: قائل کا قول کہ: ’’اللہ اس بات سے کہیں زیادہ عادل ہے کہ وہ اپنے بندے پر ظلم کرے اور اس کا ناکردہ فعل پر مواخذہ کرے۔‘‘ سو ہم اس کے موجب کا قول کرتے ہیں کہ نہ تو اللہ نے اپنے بندے پر ظلم کیا ہے اور نہ کسی ناکردہ فعل پر اس کی گرفت کی ہے۔ سوائے اس فعل کے جو بندہ اپنے اختیار اور قوت کے ساتھ کرتا ہے نا کہ اس پر جو دوسری مخلوق نے کیا ہے۔
رہا رب تعالیٰ کا ہر شی کا خالق ہونا تو یہ بندے کے ظلم پر ملوم (ملامت زدہ) ہونے کو مانع نہیں، جیسا کہ دوسری مخلوقات اس کے ظلم و عدوان پر اسے ملامت کرتی ہیں حالانکہ وہ اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ بندے کے افعال کا خالق ہے۔
اب جمہور امتیں تقدیر کا اقرار کرتی ہیں اور مانتی ہیں کہ اللہ ہر شے کا خالق ہے اور اس کے باوجود وہ ظالموں کی مذمت بھی کرتی ہیں اور ان کے ظلم و عدوان کو دفع کرنے کے لیے ان پر عقاب بھی کرتی ہیں جیسا کہ وہ اس بات کا بھی اعتقاد رکھتے ہیں اللہ مضر حیوانات و نباتات کا بھی خالق ہے اور وہ اس اقرار کے ہوتے ہوئے بھی ان نباتات وغیرہ کے ضر و شر کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر سب کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ کاذب و ظالم اپنے ظلم و کذب کی وجہ سے مذموم ہے اور یہ اس میں ایک برا وصف ہے اور یہ کہ ظلم و کذب سے متصف نفس خبیث اور ظالم ہوتا ہے جو کسی ایسے اکرام کا مستحق نہیں ہوتا جو اہلِ صدق و عدل کے مناسب ہو۔ اگرچہ وہ اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ یہ سب مخلوق ہے۔
لوگ اس فطرت پر پیدا نہیں کیے گئے کہ وہ ظالم کے ظلم کا مقابلہ اس پر ظلم کر کے کریں چاہے وہ تقدیر کے مقر بھی ہیں تب پھر اللہ بدرجہ اولیٰ اس بات کا مستحق ہے کہ ظلم کی اس کی طرف نسبت نہ کی جائے۔ یہ اہلِ سنت میں سے اہلِ حکمت و تعلیل کا طریق ہے جبکہ اہلِ مشیت و تفویض کے طریق پر ظلم اس کی ذات سے بالذات ممتنع ہے کیونکہ ظلم یہ غیر کی ملک میں تصرف کا یا اپنی ملک سے تجاوز کرنے کا نام ہے اور رب تعالیٰ کے حق میں یہ دونوں باتیں ہی ممتنع ہیں غرض رب تعالیٰ ہر حال میں اپنی ذات و صفات اور افعال میں اپنی مخلوق کے ہرگز بھی مماثل نہیں ہے بلکہ اس کے لیے تو مثل اعلیٰ ہے۔ لہٰذا جو کمال بھی غیر اللہ کے حق میں ثابت ہے، وہ اس کے حق میں بدرجہ اولیٰ ثابت ہے اور مخلوق جس نقص سے منزہ ہے، وہ اس نقص و عیب سے بدرجہ اولیٰ منزہ ہے اور ایک قادر و غنی کے جو بھی مناسب ہے رب تعالیٰ بدرجہ اولیٰ مستحق ہے کہ وہ اس کے مناسب ہو۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ جو بھی اس ذات سے قبیح ہو جو اس کے حق میں مضر ہو، وہ اس سے قبیح بھی ہو کیونکہ بندے نہ تو اس حد کو پہنچ سکے ہیں کہ اسے ضرر پہنچا سکیں اور نہ اس حد تک جا سکے ہیں کہ اسے نفع پہنچا سکیں۔
چہارم: یہ کہا جائے کہ مسلمانوں میں اس بات میں کوئی نزاع نہیں ہے کہ اللہ عادل ہے اور ظالم نہیں اور یہ کہ ہر وہ چیز جو بندے سے ظلم ہو، ضروری نہیں کہ وہ اللہ سے بھی ظلم ہو اور نہ یہ کہ جو بات بندوں سے قبیح ہو وہ رب تعالیٰ سے بھی قبیح ہو کیونکہ اس کے مثل جیسی کوئی چیز نہیں نہ ذات میں نہ صفات میں اور نہ افعال میں۔
اس کی تحقیق یہ ہے کہ اگر بات یوں ہی ہوتی جیسا کہ اسے قدریہ کہتے ہیں تو لازم آتا کہ اس سے متعدد قبیح امور بھی صادر ہوں جن کو اس نے کیا ہو کیونکہ اب بندہ بھی جب دوسرے کو کسی ایسے امر کا حکم دیتا ہے جس سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر وہ اس پر سزا کی دھمکی بھی دیتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ مامور یہ امر بجا نہ لائے گا اور نافرمانی کرے گا اور مستحق عقاب ہو گا۔ تو یہ اس سے عبث اور قبیح ہو گا کیونکہ اس میں مامور اور امر دونوں کا کوئی فائدہ نہیں ۔
اسی طرح اگر وہ یہ کہے کہ میری مراد مامور کی مصلحت ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس پر مامور کی کوئی مصلحت مرتب نہیں ہوتی بلکہ اس میں اس کا مفسدہ ہے تو بھی یہ اس سے قبیح ہو گا۔ اسی طرح اگر کوئی کسی مراد کے لیے ایک فعل کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ مراد حاصل نہ ہوگی تو ایسا فعل بھی اس سے قبیح ہو گا اسے قدریہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کفار کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ انہیں فائدہ دے اور ان کا اکرام کرے اور انہیں پیدا کر کے یہ جانتے ہوئے بھی امر دیا کہ یہ امر ان کے حق میں کسی نفع و ضرر کو نہیں رکھتا۔ اسی طرح ایک بندہ جب یہ دیکھتا ہے اس کے غلام یا باندیاں زنا میں لگے ہیں اور ظلم کے رسیا ہیں اور وہ انہیں روک بھی سکتا ہے پھر بھی انہیں نہیں روکتا تو وہ مذموم اور گنہگار اور برا ہو گا، حالانکہ اللہ مذموم و مسیئی ہونے سے منزہ ہے۔
یہ قدری کہتا ہے کہ اللہ نے انہیں پیدا کرنے سے اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ وہ اس کی اطاعت کریں اور یہ انہیں ثواب دے۔ پس اللہ نے انہیں نفع کے لیے پیدا کیا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ نفع نہ اٹھائیں گے۔ حالانکہ یہ بات معلوم ہے کہ ایسی بات خلق سے قبیح ہے اور خالق سے قبیح نہیں ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ جب مخلوق اپنے غلاموں کو قبائح سے روکنے پر قادر ہو، تو اس کا انہیں روکنا یہ اس بات سے بہتر ہے کہ وہ انہیں ثواب پر پیش کرے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ انہیں صرف عقاب ہی حاصل ہو گا۔ جیسے وہ شخص جو اپنے بیٹے یا غلام کو نفع کے حصول کے لیے مال دے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس مال سے صرف زہر خرید کر ہی کھائیں گے تو اس کے انہیں مال نہ دینا اس بات سے بہتر ہے کہ وہ انہیں مال دے۔ حالانکہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ اس مال سے صرف ضرر ہی اٹھائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی دوسرے کو کفار سے قتال کرنے کے لیے تلوار دے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ اس تلوار سے صرف پیغمبروں اور مومنوں سے ہی لڑے گا تو اس کا انہیں تلوار دینا اس سے قبیح ہو گا اور اس نے یہ کہا کہ میرا قصد اسے ثواب پر پیش کرنا تھا اور اللہ سے یہ قبیح نہیں ہے۔
سو ان قدریہ کے نزدیک بندے کی قدرت کا یہ حال ہے اور افعال سے تشبیہ دینے والے قدریہ رب تعالیٰ کے افعال کو اسکی مخلوق کے افعال سے تشبیہ دیتے ہیں اور ان پر قیاس کرتے ہیں اور اس کے عدل کو بندوں کے عدل پر قیاس کرتے ہیں۔ بلاشبہ یہ بدترین فاسد قیاس ہے۔
پنجم: یہ کہا جائے کہ معصیت بندے سے ہے جیسا کہ طاعت بھی اسی سے ہوتی ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ جب بندے سے اطاعت ہونا بایں معنیٰ ہے کہ بندے نے اپنی قدرت و مشیت سے یہ اطاعت بجا لائی ہے تو یہ بات ممتنع نہ ہو گی اللہ نے اسے اپنی قدرت و مشیت کے ساتھ اطاعت کا فاعل بنایا ہے بلکہ عقل و شرع دونوں اس پر دلالت کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت خلیل علیہ السلام کا ارشاد ہے
رَبِّ اجۡعَلۡنِىۡ مُقِيۡمَ الصَّلٰوةِ وَمِنۡ ذُرِّيَّتِىۡ رَبَّنَا وَتَقَبَّلۡ دُعَآءِ ۞(سورۃ ابراهيم: آیت، 40)
ترجمہ: ’’اے میرے رب! مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی۔‘‘
اور فرمایا: وَ جَعَلۡنَا مِنۡهُمۡ اَئِمَّةً يَّهۡدُوۡنَ بِاَمۡرِنَا۞ (سورۃ السجدة: آیت، 24)
ترجمہ: ’’اور ہم نے ان میں سے کئی پیشوا بنائے، جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے۔‘‘
اس لیے بھی کہ بندے کا فاعل ہونا بعد اس بات کے کہ وہ فاعل نہ تھا کہ یہ ایک امر حادث ہے اور امرِ حادث کے لیے ایک محدث کا ہونا لازم ہے اور بندے کے حق میں یہ بات ممتنع ہے کہ وہ اپنے فاعل ہونے کا فاعل بھی وہ خود ہو کیونکہ اس کا فاعل ہونا اگر تو اس کے نفس فاعل ہونے سے حادث ہوا ہے تو لازم آئے گا کہ ایک چیز بغیر پیدا کرنے والے کے از خود پیدا ہو گئی ہو اور یہ بات ممتنع ہے اور اگر وہ کسی دوسری فاعلیت کی بنا پر فاعل ہوا ہے پھر اگر تو یہ دوسری فاعلیت پہلی فاعلیت سے پیدا ہوئی ہے تو اس سے دورِ قبلی لازم آئے گا اور اگر یہ پہلی فاعلیت کے بغیر حادث ہوا ہے تو امورِ متناہیہ میں تسلسل لازم آئے گا اور یہ دونوں باتیں ہی باطل ہیں۔
پس معلوم ہوا کہ بندے سے ایسی طاعت و معصیت کا ہونا کہ جس سے وہ مدح و ذکر اور ثواب و عقاب کا مستحق ٹھہرے، یہ اس بات کو مانع نہیں کہ وہ ہر بات رب تعالیٰ کا محتاج ہو اور کسی بابھی اس سے بے نیاز نہ ہو اور یہ کہ اس کے جملہ امور کا خالق اللہ ہو اور یہ کہ بندے کے حوادث و ممکنات میں سے نفس افعال اللہ کی قدرت و مشیت کی طرف منسوب ہوں ۔