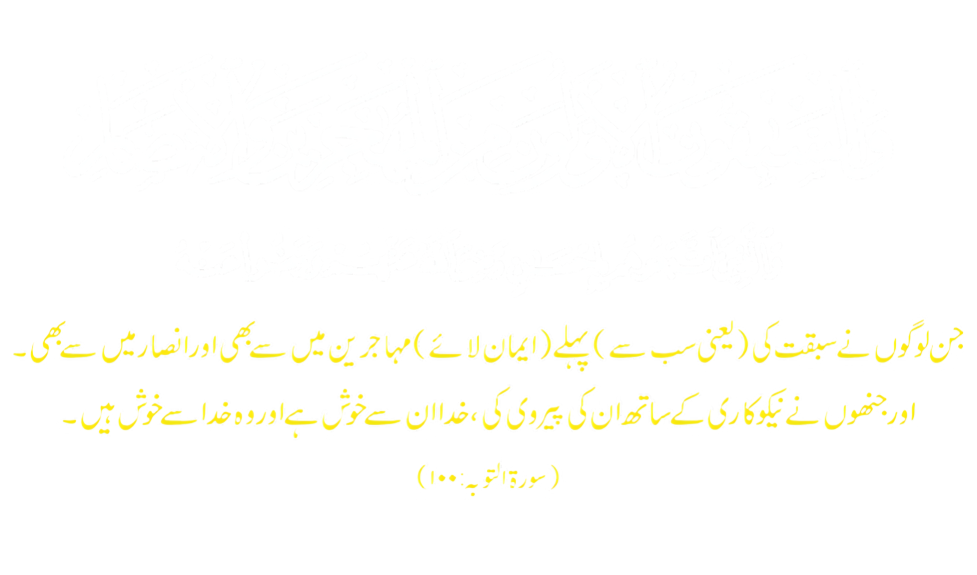فصل: ....حدیث میں مہارت کی ضرورت
امام ابنِ تیمیہؒفصل: ....حدیث میں مہارت کی ضرورت
[اہل نظر و استدلال میں ہر کوئی منقولات کا خبیر اورجھوٹ اورسچ اور صحیح اور سقیم کے مابین فرق کا ماہر نہیں ہوتا]
جان لیجیے کہ : اہل نظر و استدلال میں ہر کوئی منقولات کا خبیر اورجھوٹ اورسچ اور صحیح اور سقیم کے مابین فرق کا ماہر نہیں ہوتا؛عوام الناس کی تو بات ہی کجا ہے۔اور اجمالی طور پر یہ بات معلوم شدہ ہے کہ منقولات میں سچ بھی ہوتا ہے اور جھوٹ بھی۔ اور ان حضرات کو علم حدیث کے ماہر علماء کی طرح کا علم اور تجربہ نہیں ہوتا۔ پس انہیں حضرات کو جھوٹ اور سچ پر استدلال کرنے کے لیے دوسرے طریقوں کی ضرورت ہوتی ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم کے ذریعہ تعلیم دی ہے؛ اور انسان کو وہ کچھ سکھایا ہے جو وہ نہیں جانتا تھ۔ اور اسے پیدا کیا؛ پھر برابر کیا؛ جس نے تقدیر مقرر کی اور ہدایت دی۔ اورہر چیز کو اس کے مناسب حال پر پیدا کیااور پھر اس کو ہدایت دی۔ وہ ہستی جس نے لوگوں کوان کی ماؤں کے پیٹوں سے نکالا؛اوروہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے؛ اور پھران کے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنادیے ؛ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے ان دلائل کی طرف آسانی سے ہدایت دیتا ہے جن کی وجہ سے حق اور باطل اور سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز کرنا ممکن ہو۔
جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے :
’’ اے میرے بندو! تم سارے گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دیدوں ۔پس تم مجھ سے ہدایت طلب کرو‘ میں تمہیں ہدایت دوں گا۔‘‘
یہی وجہ ہے کہ جھوٹ سے سچ کی معرفت کے مختلف طریقے ہیں ۔ حتی کہ کوئی خبر دینے والا اپنی ذات کے بارے میں یہ خبر دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے۔ یعنی وہ نبوت کا دعوی کرتا ہے۔ پس وہ طرق جن کے ذریعہ سچے کی سچائی اور جھوٹے کذاب متنبی کی معرفت ہو؛ بہت زیادہ اور مختلف ہیں ۔ اس مسئلہ پر ہم کئی ایک مواقع پر تنبیہ کرچکے ہیں ۔ یہی حال رسولوں سے منقول پیغام کا بھی ہے۔ ان میں سے سچ اور جھوٹ کے جاننے کے طریقے متعدد اور متنوع ہیں ۔ اور یہی حال ان لوگوں کی صداقت جاننے کا بھی ہے جو اس علم نبوت کے حاملین ہیں ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل علم سچوں کی سچائی کو جانتے ہیں ۔ جیسا کہ امام مالک، اورالثوری، شعبہ، یحی بن سعید؛ عبد الرحمن بن مہدی؛ أحمد بن حنبل، البخاری، مسلم، ابو داود، اور ان کے امثال علماء کے متعلق علم یقینی کے طور پر جانتے ہیں ؛ اور پورے وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ : یہ حضرات جان بوجھ کرحدیث میں جھوٹ نہیں بولتے ۔اور ان کے مقابلہ میں محمد بن سعید المصلوب، ابو البختری القاضی، واحمد بن عبد اللہ الجویباری، وعتاب بن براہیم بن عتاب، ابو داود النخعی،اور ان جیسے دوسرے لوگوں کے متعلق جانتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں ۔
لیکن جہاں تک خطاء کا تعلق ہے ؛تو اس پر نبی کو باقی نہیں رہنے دیا جاتا؛ ان کے علاوہ کوئی بھی خطا سے معصوم نہیں ۔ لیکن محدثین کرام جانتے ہیں کہ ائمہ جیسا کہ زہری ؛ ثوری ؛ مالک اور ان کے امثال بہت معمولی چیزوں میں سب لوگوں سے کم غلطی کرنے والے ہیں ۔ اوریہ چیزیں بھی ایسی معمولی ہیں کہ اس سے حدیث کے مقصود میں فرق نہیں آتا۔ اوروہ ان سے کم مرتبہ کے ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں جن سے کبھی کبھار غلطی ہوجاتی ہے؛ مگر اکثر طور پر ان پر حفظ اور ضبط کا غلبہ رہتا ہے۔ اور ان کے پاس ایسے دلائل ہوتے ہیں جن سے غلطی کرنے والے کی غلطی پر استدلال کرتے ہیں ۔
ان کے علاوہ کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ غلطی کرتے ہیں ۔ یہ لوگ جب کسی روایت کے نقل کرنے میں منفرد ہوں تو ان سے استدلال نہیں کیا جاتا۔لیکن ان کی روایت کردہ حدیث کو بطور شاہد اور اعتبار کے تسلیم کیا جاتا ہے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی روایت میں دیکھا جاتا ہے۔کیا ان کے علاوہ کسی اور نے بھی روایت کیا ہے یانہیں ؟
جب اس کی اسناد متعدد ہوں ‘ اور الفاظ ایک ہوں ؛ اور یہ بھی علم ہو کہ انہوں نے آپس میں ملاقات یا عمدا ایسا نہیں کیا۔ اور عام طور پر اس جیسے معاملات میں خطا نا ممکن ہو تو یہ اس حدیث کے سچا ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔
اسی لیے امام أحمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں : بسا اوقات کسی آدمی سے حدیث کی روایت میں اعتبار [و شاہد] کے لیے لکھ لیتا ہوں ۔ جیسا کہ ابن لھیعہ اور ان جیسے دوسرے لوگ ۔اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عالم و فاضل ؛ دیندار قاضی تھا۔ لیکن اس کی کتابیں جل گئی تھیں ۔ پھر اس کے بعد جو حدیث بیان کرتا ؛ان میں بہت کچھ غلطی کرجاتا ۔ لیکن اس کی اکثرروایت صحیح ہوتی ہیں جن پر دوسرے ثقہ علماء جیسے لیث رحمہ اللہ اور ان کے امثال موافقت کا اظہار کرتے ہیں ۔
اہل الحدیث[محدثین کرام] رحمہم اللہ صحیحین کے متون کی سچائی کو جانتے ہیں ۔ اور من گھڑت روایات کے جھوٹ کو بھی جانتے ہیں جن کے بارے میں وہ یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ ہیں ۔ اس کی وجہ وہ اسباب ہیں ؛ جن کی وجہ سے وہ اس علت کو جانتے ہیں ۔ اور وہ لوگ بھی جانتے ہیں ؛جو اس علم میں ان کے ساتھ شریک ہیں ۔ اور جو لوگ اس علم میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہیں وہ ان علتوں کو نہیں جانتے۔ جیسا کہ وہ گواہ جو گواہی دیتے ہیں ۔جس کو ان لوگوں کا تجربہ او رخبر ہو ؛ وہ ان کے سچے کی سچائی ؛اور جھوٹے کے جھوٹ کو جانتے ہیں ۔ یہی حال تجارتی معاملات خرید و فروخت اور کرایہ داری میں تجربہ اور علم رکھنے والے جھوٹے کا جھوٹ؛ سچے کی سچائی اور امانت دار او رخائین کو جانتے ہیں ۔ یہی حال ان واقعات کا بھی ہے جن میں بعض کے سچ ہونے کو اور بعض کے جھوٹ ہونے کو لوگ اچھی طرح جانتے ہیں ۔ اور بعض معاملات میں وہ شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخبار و احوال کی معرفت؛ آپ کے اقوال و افعال؛ آپ کی بیان کردہ توحید؛ امر و نہی ؛وعد و وعید اوراعمال و اقوام اور زمان و مکان کے فضائل و مثالب [نقص و عیب]کا حال بھی ایسے ہی ہے۔ان کا سب سے زیادہ علم ان لوگوں کو ہے جنہیں آپ کی احادیث کا علم ہے ؛ اور انہوں نے اس علم کے حاصل کرنے میں ہر طرح کی جدو جہد ؛ محنت ومشقت سے کام لیا ہے۔ اور اس علم کے نقل کرنے والوں کے احوال کی معرفت حاصل کی ہے۔ او رپھر کئی اعتبار و وجوہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو جانا۔اور ان سب روایات کو جمع کیا۔ اور سچے کی سچائی ؛ غلط کار کی غلطی اور جھوٹے کے جھوٹ کی معرفت حاصل کی۔
اس علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے اس امت میں ان علوم کی حفاظت کی جن کی وجہ سے یہ دین محفوظ رہا۔ اور دوسرے لوگ اس علم میں ان کے تابع ہیں : یا تو ان سے استدلال کرنے والے ہیں ؛ یا پھر ان کے مقلد ہیں ۔ جیسا کہ احکام میں اجتہاد کا معاملہ ہے؛ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا؛ حتی کہ ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ان کے دین کو محفوظ کیا۔ تو ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ؛ وہ ان کے تابع ہیں ۔ یا تو ان سے استدلال کرنے والے ہیں ؛ یا پھر ان کے مقلد ہیں ۔
مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص الخواص اصحاب کرام رضی اللہ عنہم ان لوگوں کی نسبت احوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت زیادہ رکھتے تھے جنہیں اختصاص میں ان سے کم مرتبہ ملا تھا۔ خواص کی مثال: جیسا کہ حضرت أبو بکر وعمر،عثمان، علی، طلحۃ، الزبیر،عبد الرحمن بن عوف، سعد، أبي بن کعب، معاذ بن جبل، ابن مسعود، بلال، وعمار بن یاسر، ابو ذر الغفاری، وسلمان، وأبو الدرداء، وابو یوب الأنصاری،عبادۃ بن الصامت، وحذیفہ، وأبو طلحہ،اور ان کے امثال مہاجرین و انصار میں سے سابقین اولین؛- رضی اللہ عنہم - جنہیں ان لوگوں کی نسبت زیادہ اختصاص حاصل تھا جو کہ ان کے ہم پلہ و ہم مثل نہیں ہیں ۔لیکن بعض صحابہ کرام دوسروں کی نسبت زیادہ یادداشت اور سمجھ و فقہ رکھتے ہیں ۔اگرچہ ان میں سے کسی دوسرے کو لمبی صحبت کی سعادت ملی ہو۔ اور بعض سے ان کی لمبی عمر کی وجہ سے لوگوں نے زیادہ علم حاصل کیا ہوتا ہے؛ بھلے کوئی دوسرا اس سے بڑا عالم کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ حضرت ابوہریرہ؛ حضرت ابن عمر؛ حضرت ابن عباس؛ حضرت عائشہ؛ حضرت جابر؛ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہم سے ان لوگوں کی نسبت زیادہ علم حدیث حاصل کیا گیاہے جو ان سے زیادہ افضل تھے۔ جیسے حضرت طلحہ؛ حضرت زبیر؛اور ان کے امثال رضی اللہ عنہم ۔ جب کہ خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم کو کلیات دین کی تبلیغ ؛ دین کے اصولوں کی نشرو اشاعت اور لوگوں کے ان سے علم دین کے حصول میں وہ مقام حاصل ہے جو ان کے علاوہ کسی دوسرے کے نصیب میں نہیں ۔ اگرچہ بعض صغار صحابہ سے احادیث ِ مفردہ اتنی کثرت سے روایت ہیں جو کہ خلفاء سے بھی روایت نہیں کی گئیں ۔ پس خلفائے راشدین کو عموم تبلیغ اور دین کو قوت دینے میں وہ مقام حاصل ہے جس میں کوئی دوسرا ان کا شریک نہیں ۔پھر جب یہ لوگ اس دعوت و تبلیغ کے لیے کھڑے ہوئے تو ان کے علاوہ دوسرے بھی اس بابرکت کام میں ان کے شریک ہوگئے۔ پس اس طرح اس کام کوتراتر کادرجہ حاصل ہوگیا؛ جیسا کہ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کا مصاحف کی شکل میں قرآن جمع کرنا؛پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے ایک مصحف کی شکل میں جمع کیا ۔ اور پھرمختلف شہروں میں ارسال کیا۔ پس اس وقت قرآن جمع کرنے اور اس کی تبلیغ کا اہتمام دوسرے تمام امور کی نسبت بہت زیادہ رہا ہے۔
یہی حال مختلف شہروں میں شرائع اسلام کی تبلیغ کا بھی رہا ہے۔ اور اسی چیز پر ان کے ساتھ قتال بھی ہوتا رہا۔ اور امراء و علماء اس معاملہ میں نیابت کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ اور یہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے اقوال و افعال لوگوں تک پہنچاتے رہے۔پس یہ تبلیغ ان اہل علم تک پہنچی جنہوں نے اس دین کوقائم کیا؛ اور یہ نقل نقل متواترِ ظاہر اور ایسی معلوم شدہ ہوگئی جس سے حجت قائم ہوسکے۔ اورراہِ حق بالکل واضح ہوجائے۔ اور اس سے بالکل یہ بھی واضح ہوگیا یہ حضرات ہدایت یافتہ خلفائے راشدین تھے جو علم و عمل کے لحاظ سے اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بنے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ؛ جیسا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں ارشاد فرماتے ہیں :
﴿وَالنجم اِِذَا ہَوٰیo مَا ضَلَّ صَاحِبُکُمْ وَمَا غَوٰیo وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْہَوٰیo اِِنْ ہُوَ اِِلَّا وَحْیٌ یُّوحٰیo﴾[النجم۱۔۴]
’’قسم ہے ستا رے کی جب وہ گرے ! کہ تمھارا ساتھی (رسول) نہ راہ بھولا ہے اور نہ غلط راستے پر چلا ہے۔ اور نہ وہ اپنی خواہش سے بولتا ہے۔ وہ تو صرف وحی ہے جو نازل کی جاتی ہے ۔‘‘
پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی راہ سے ہٹے؛ اور نہ ہی بہکے۔ یہی حال خلفائے راشدین کا بھی تھا۔جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :
((علیکم بسنتي و سنۃ خلفاء الراشدین المہدیین من بعدي تمسکوا بہا و عضوا علیہا بالنواجذ۔و إیّاکم ومحدثات الأمور؛ فإن کل بدعۃ ضلالۃ۔))
’’ تم پر میری سنت اور میرے بعد میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے ۔ اس کے ساتھ چمٹے رہو ‘ اور اسے اپنے کنچلی کے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو۔خبردار! اپنے آپ کو نئے کاموں سے بچاکر رکھنا ؛ اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔‘‘ [سنن أبي داؤد ۴؍۴۸۰۰؛ وابن ماجۃ ۱؍۱۵۔ والدارمي ۱؍۴۴۔]وقد سبق تخریجہ]
بلا شک و شبہ خلفائے راشدین اس مہم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے؛ بنابرایں ہدایت کی وجہ سے ان سے گمراہی کی نفی کی گئی ہے اور رشد وکامیابی کی وجہ سے کجی اوربے راہ روی کی نفی کی گئی ہے۔
یہ علم و عمل کا کمال ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ گمراہی علم نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور کجی اتباع نفس [خواہشات نفس کی پیروی] کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پس اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نمازوں میں یوں کہیں :
﴿اِہْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْم(۵) صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ (۶) غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْہِمْ وَ لَا الضَّآلِّیْنَ﴾[الفاتحہ ۶۔۷]
’’ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں ۔‘‘
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :’’مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور الضالین سے مراد نصاری ہیں ۔‘‘
پس ہدایت یافتہ اورکامیاب وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیدیں ۔اور وہ اہل ضلال جاہلوں میں سے نہ ہو۔اور نہ ہی ان سرکش اور باغیوں میں سے ہو جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔
یہاں پر مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بعض دوسرے صحابہ کرام کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کی معرفت زیادہ رکھتے تھے۔اور بعض نے دوسروں سے سیکھ کر تبلیغ میں زیادہ کردار ادا کیا۔ پھر بسا اوقات مفضول کے پاس کسی خاص مسئلہ میں وہ علم ہوتاہے جو افضل کے پاس نہیں ہوتا؛ سو وہ افضل اس علم میں مفضول سے مستفید ہوتاہے۔ اس سے یہ واجب نہیں ہوتا کہ مفضول فاضل سے مطلق طور پر بڑا عالم ہو۔ اور نہ ہی یہ فاضل جو مفضول سے علم حاصل کررہا ہے؛ اس وجہ سے اعلم و افضل اور ممتاز ہوجاتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم بعض ان مسائل میں جن کا علم ان کے پاس نہ ہوتا؛ عام صحابہ کرام سے مستفید ہوا کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دادی کی میراث کے علم میں محمد بن مسلمہ ، اورمغیرہ بن شعبہ سے استفادہ کیا۔ اورحضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جنین کی دیت؛استئذان ؛اور شوہر کی دیت سے بیوی کی میراث کے بارے؛اور کچھ دوسرے مسائل میں دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے استفادہ کیا۔اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیوہ کی عدت گزاری؛ اورحضرت علی رضی اللہ عنہ نے صلاۃ توبہ کے بارے میں دوسرے صحابہ کرام سے استفادہ کیا۔
بسا اوقات علم فاضل پر مخفی رہتاہے؛اور اس کی موت تک اسے اس کا علم نہیں ہوتا۔لیکن علم کی اس بات کی تبلیغ وہ لوگ کرتے ہیں جو اس عالم و فاضل سے کم مرتبہ ہیں ۔اور ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ موقع ان چیزوں کو بیان کرنے کا نہیں ۔ لیکن یہاں پر مقصود علم کے طرق کا بیان کرنا ہے۔ پس خلفائے راشدین کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسے : حضرت أ بی بن کعب، اورابن مسعود، اورمعاذ بن جبل، اور ابو الدرداؤ، اورزید بن ثابت، وحذیفہ، وعمران بن حصین، و أبوموسیٰ وسلمان، وعبد اللہ بن سلام، اور ان کے امثال و ہم پلہ حضرات سے لوگوں نے علم حاصل کیا۔
پھر ان کے بعد جیسا کہ حضرت عائشہ، ابن عباس، ابن عمر، عبد اللہ بن عمرو ابو سعید، وجابر رضی اللہ عنہم ، اور دوسرے حضرات کا مرتبہ آتا ہے۔
تابعین میں سے فقہاء کرام اور دوسرے تابعین جیسا کہ سعید بن مسیب، عروہ بن الزبیر، عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ،القاسم بن محمد، وسالم بن عبد اللہ، ابو بکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام،علی بن الحسین، وخارجہ بن زید بن ثابت، اورسلیمان بن یسار رحمہم اللہ ، اورجیسا کہ علقمہ، أسود، شریح القاضی، عبیدہ السلمانی، والحسن البصری، ومحمد بن سیرین رحمہم اللہ ،اور ان کے أمثال۔
پھر ان کے جیسے الزہری، وقتادہ، یحی بن أبی کثیر؛ مکحول الشامی، اورایوب السختیانی، یحی بن سعید الأنصاری، یزید بن أبی حبیب المصری رحمہم اللہ ،اور ان کے أمثال۔
پھر ان کے بعد جیسے:امام مالک ، ثوری، حماد بن زید، حماد بن سلمہ، اللیث، أوزاعی، شعبہ، اورزائدہ، اورسفیان بن عیینہ،اور ان کے أمثال۔ رحمہم اللہ
پھر ان کے بعد جیس: یحی القطان، عبد الرحمن بن مہدی، ابن المبارک، عبد اللہ بن وہب، وکیع بن الجراح، اسماعیل بن علی، ہشیم بن بشیر رحمہم اللہ ۔
پھر ان کے بعد : امام بخاری، مسلم، أبو داود، أبو زرعہ، أبو حاتم، عثمان بن سعید الدارمی،وعبد اللہ بن عبد الرحمن الدارمی، ومحمد بن مسلم بن وارہ، أبو بکر الأثرم، ابراہیم الحربی، وبقی بن مخلد أندلسی، ومحمد بن وضاح۔ رحمہم اللہ
پھر جیساکہ: ابو عبد الرحمن النسائی،الترمذی، ابن خزیمہ، ومحمد بن نصر المروزی، ومحمد بن جریر الطبری، وعبد اللہ بن أحمد بن حنبل، وعبد الرحمن بن أبی حاتم رحمہم اللہ ۔
پھر ان کے بعد جیسے:ا بوحاتم البستی،اور أبو بکر النجاد، وأبو بکر نیساپوری، وأبو قاسم الطبرانی، أبو الشیخ الأصفہانی، أبو أحمد العسال الأصفہانی، اور ان کے امثال۔ رحمہم اللہ
پھر ان کے بعد جیسے :ابو الحسن الدارقطنی، ابن مندہ، الحاکم أبو عبد اللہ، عبد الغنی بن سعید، رحمہم اللہ اور ان کے امثال ؛اتنے لوگ ہیں کہ ان کا اعداد و شمار ہی ممکن نہیں ۔
یہ حضرات اور ان کے امثال لوگوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کی معرفت رکھتے ہیں ۔اگرچہ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جن کی روایات دوسروں سے بہت زیادہ تھیں ۔ اور ان میں ایسے بھی تھے جنہیں دوسروں کی نسبت صحیح اور ضعیف حدیث کی معرفت زیادہ تھی۔اور ایسے بھی تھے جو دوسروں سے بڑھ کر فقیہ تھے۔
امام أحمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں : ’’ حدیث کی معرفت اور اس کی سمجھ حاصل کرنا میرے نزدیک حدیث کوزبانی یاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔
علی بن المدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں : ’’ متون الحدیث سے علم فقہ اور راویوں کے احوال کی معرفت حاصل کرنا تمام علوم سے بہتر علم ہے۔‘‘
اس میں کوئی شک نہیں کہ یحی بن معین اور علی المدینی اور ان کے امثال صحیح اور سقیم حدیث کی معرفت میں ابو عبید اور ابو ثور سے بڑے عالم ہیں ۔ جب کہ ابو عبید او رابو ثور علم فقہ میں ان سے بڑے عالم ہیں ۔ اور امام احمد بن حنبل ان دونوں قسم کے افراد کے ساتھ ان کے علوم میں شریک ہیں ۔ ان دونوں قسم کے علوم کے ائمہ امام احمد سے محبت کرتے تھے؛ اور امام صاحب ان سے محبت کرتے تھے۔ جیسا کہ امام شافعی اور ابو عبید رحمہما اللہ اور ان کے امثال اہل فقہ فی الحدیث کے ساتھ آپ کا عالم تھے؛ اور جیسا کہ یحی بن معین اور علی بن المدینی رحمہما اللہ اور ان کے امثال علوم حدیث کی معرفت رکھنے والوں کے ساتھ ان کا سلوک رہا ہے۔
مسلم بن حجاج رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح مسلم میں ابو داؤد رحمہ اللہ کی نسبت احادیث کی صحت کا زیادہ اہتمام کیا ہے۔ جب کہ ابوداؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ’’السنن ‘‘میں فقہ کا اہتمام زیادہ کیا ہے۔ جب کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان دونوں چیزوں کا خیال رکھاہے۔
یہاں پر مقصود ان باتوں میں کلام کو وسعت دینا نہیں ۔ بلکہ مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ علم حدیث رکھنے والے علماء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کی معرفت دوسروں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ وہ اس میدان کے امام ہیں ۔ بیشتر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان سچا ہوتا ہے؛ اور اس کی روایات ِ حدیث بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں ۔ لیکن اس کے ہاں صحیح اور سقیم کی معرفت کا اہتمام نہیں پایا جاتا۔ پس اس کی نقلِ روایت سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے؛ کیونکہ سچا اور بات کو یاد رکھنے والا ہے۔جب کہ صحیح اور سقیم کی معرفت ایک دوسرا علم ہے۔ اور بیشتر اوقات کوئی ایک اس کے ساتھ ہی فقہی اور مجتہد ہوتا ہے اور کوئی انسان نیک اور اچھے مسلمانوں میں سے ہوتا ہے لیکن اس کی معرفت اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔
لیکن یہ لوگ اگرچہ علم میں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں ؛ اور ان میں جھوٹ کو ایسے پذیرائی نہیں ملتی جیسے ان لوگوں میں اسے پذیرائی مل جاتی ہے جنہیں علم نہ ہو۔ لیکن یہاں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جس کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کی معرفت جتنی زیادہ ہوگی ؛ اسے سچ اور جھوٹ کے مابین تمیز کرنے کی صلاحیت بھی اتنی ہی زیادہ حاصل ہوگی۔ کبھی اہل تفسیر ؛ اہل فقہ و زہد اور مناظرین کے مابین بہت سی احادیث مشہور ہوتی ہے؛ جن کو یا تو وہ خود سچ کہتے ہیں یا پھر ان کے سچا ہونے کو جائز سمجھتے ہیں ۔ جب کہ علم حدیث کے ماہرین علماء[محدثین] کے ہاں وہ روایت جھوٹ ہوتی ہے۔
بسا اوقات یہ حضرات ایسی حدیث کو صحیح کہتے ہیں جو محدثین[ماہرین حدیث] کے نزدیک جھوٹ ہوتی ہے۔ مثلاً وہ حدیث جسے فقہاء کرام کا گروہ نقل کرتا چلا آیا:
((لا تفعلِی یا حمیراء فإِنہ یورِث البرص۔))
’’اے حمیرا! ایسے نہ کرنا؛ بیشک اس سے برص پیدا ہوتا ہے ۔‘‘
اورحدیث: ((زکاۃ الأرضِ نبتہا۔))
’’زمین کی زکات اس کی نباتات [پیداوار ہیں ]۔‘‘
اورحدیث: (( نہِی عن بیع وشرط، ونہِی عن بیعِ المکاتبِ والمدبرِ وأمِ الولدِ۔))
’’آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرید نے اور شرط لگانے سے منع کیا؛ اور منع فرمایا کہ مکاتب اور مدبر یا ام ولد کو بیچا جائے ۔
اورحدیث:((نہِی عن قفِیزِ الطحان))۔
’’چکی والے کی کمائی لینے سے منع فرمایا۔‘‘
اورحدیث: (( لا یجتمِع العشر والخراج علی مسلِم۔))
’’ ایک مسلمان پر خراج اور عشر جمع نہیں ہوسکتے۔
اورحدیث:(( ثلاث ہن علی فرِیضۃ، وہن لکم تطوع: الوِتر والنحر ورکعتا الفجرِ ۔))
’’تین چیزیں مجھ پر فرض ہیں اور تمہارے لیے نفل ہیں ؛ وتر کی نماز ؛ قربانی کرنا؛ فجر کی دو سنتیں ۔‘‘
اورحدیث: ((کان رسول اللہِ رضی اللہ عنہم فِی السفرِ یتِم ویقصر ۔))
’’رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں پوری نماز بھی پڑھتے تھے اور قصر بھی کرتے تھے۔‘‘
اورحدیث: (( لا تقطع الید ِإلا فِی عشرۃِ دراہِم ۔))
’’دس درہم سے کم میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔‘‘
اورحدیث: ((لا مہر دون عشرۃِ دراہِم۔))
’’دس درہم سے کم مہر نہیں ہوتا۔‘‘
اورحدیث: ((الفرق بین الطلاقِ والعِتاقِ فِی الِاستِثناِ....۔))
’’طلاق اور آزاد کرنے میں فرق استثناء کا ہے ۔‘‘
اورحدیث: (( أقل الحیضِ ثلاثۃ وأکثرہ عشرۃ۔))
’’حیض کی کم سے کم مدت تین دن او رزیادہ سے زیادہ دس دن ہے۔‘‘
اورحدیث: (( نہی عنِ البترائِ۔))
’’آپ نے دم کاٹنے سے منع فرمایا۔‘‘
اورحدیث: (( یغسل الثوب مِن المنِیِ والدمِ ۔))
’’ منی او رخون سے کپڑا دھو لیا جائے گا۔‘‘
اورحدیث: ((الوضوء مِما خرج لا مِما دخل ۔))
’’ وضوء اس چیز سے ہے جو خارج ہو ؛ نہ کہ اس پر جو داخل ہو۔‘‘
اورحدیث: ((کان یرفع یدیہِ فِی ابتِدائِ الصلاِۃ ثم لا یعود۔))
’’نماز کے شروع میں رفع الیدین کیا کرتے تھے؛ پھر نہیں کرتے تھے۔‘‘
اس طرح کی دیگر احادیث بھی ہیں جنہیں فقہاء کرام کے ایک گروہ نے صحیح کہا ہے ؛ اوروہ ان کی تصدیق کرتے ہیں اور ان پرحلال و حرام کی بنیاد قائم کرتے ہیں ۔ جب کہ حدیث کا علم رکھنے والے اس بات پر متفق ہیں کہ یہ روایات جھوٹ ہیں اور اپنی طرف سے گھڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہیں ۔ اور اہل فقہائے کرام رحمہم اللہ بھی یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں ۔ اور یہی حال ان روایات کا بھی ہے جنہیں نساک و عبّاد روایت کرتے ہیں ؛ اور خیال کرتے ہیں کہ یہ احادیث سچی ہیں ۔ مثال کے طور پر یہ روایت :
((إِن عبد الرحمنِ بن عوف یدخل الجنۃ حبواً۔))
’’ بیشک عبد الرحمن بن عوف سرینوں کے بل چلتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے ۔‘‘
اس فرمان الٰہی کے بارے میں ان کا یہ کہنا کہ:
﴿وَ لَا تَطْرُدِ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ رَبَّہُمْ بِالْغَدٰوۃِ وَ الْعَشِیِّ یُرِیْدُوْنَ وَجْہَہٗ﴾[الانعام: 52]
’’اور ان لوگوں کو دور نہ ہٹا جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں ، اس کی رضا چاہتے ہیں ۔‘‘
اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان :
﴿وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ رَبَّہُمْ بِالْغَدٰوۃِ وَ الْعَشِیِّ یُرِیْدُوْنَ وَجْہَہٗ ﴾[الکہفِ: 28]
’اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ روکے رکھ جو اپنے رب کوصبح وشام پکارتے ہیں اس کی رضا چاہتے ہیں ۔‘‘
ان کا کہنا ہے کہ یہ آیات اہل صفہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اور مثال کے طور پر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے غلام کے متعلق یہ روایت :
((غلام المغِیرۃِ بنِ شعبۃ أحد الأبدالِ الأربعِین۔))
’’ مغیرہ بن شعبہ کاغلام چالیس ابدالوں میں سے ایک ہے۔‘‘
یہی حال ان روایات کا بھی ہے جن میں ابدال ؛ اقطاب؛ غواث؛ اور اولیاء کی تعداد کا ذکر ہے۔ اور ان کے امثال دوسری روایات ؛ جن کے متعلق ماہرین علم حدیث جانتے ہیں کہ یہ روایات جھوٹ ہیں ۔
ان کی امثال دوسری روایات ؛ ان احادیث کے بارے دوسرے کئی طریقوں سے بھی معلوم ہوسکتا ہے کہ یہ جھوٹ ہیں ۔ مثلاً ہم جانتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ :
﴿وَ لَا تَطْرُدِ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ رَبَّہُمْ بِالْغَدٰوۃِ وَ الْعَشِیِّ یُرِیْدُوْنَ وَجْہَہٗ﴾[الانعام: 52]
اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان :
﴿وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ رَبَّہُمْ بِالْغَدٰوۃِ وَ الْعَشِیِّ یُرِیْدُوْنَ وَجْہَہٗ ﴾[الکہفِ: 28]
یہ آیات سورۃ انعام اور سورت کہف میں ہیں ۔ اور یہ دونوں سورتیں بالاتفاق مکی ہیں ۔ اور صفہ مدینہ میں تھا ۔اور ایسے ہی وہ حدیث معراج جس میں کہا گیا ہے کہ آپ نے معراج کی رات اپنے رب کو ایسی صورت میں دیکھا ۔ جب کہ معراج کی وہ احادیث جو صحاح کی کتابوں میں ہیں ؛ ان میں رؤیت نام کی کوئی چیز نہیں ؛ رویت کی احادیث مدینہ کی ہیں ۔جیسا کہ حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث میں ہے:
((أتانِی البارِحۃ ربِی فِی أحسنِ صورۃ....إِلی آخِرِہِ۔))
’’میرے رب تعالیٰ رات میرے پاس خوبصورت شکل میں آئے ....‘‘
یہ خواب آپ نے مدینہ طیبہ میں دیکھا تھا۔ اور یہی حال اس کے متشابہ دوسرے خوابوں کا ہے؛ وہ تمام کے تمام آپ نے مدینہ طیبہ میں دیکھے تھے۔ جبکہ واقعہ معراج مکہ مکرمہ میں پیش آیا تھا؛ اس پر نصوص قرآن کی روشنی میں تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔
بسا اوقات کوئی حدیث کسی گروہ کے ہاں رواج پاتی ہے؛ جس کا جھوٹ ہونا انتہائی ظاہر ہوتا ہے۔ مثلاً یہ روایت کہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجد میں آگئے حتی کہ بردہ آپ سے گرگیا۔‘‘ اس روایت کے من گھڑت جھوٹ ہونے پر تمام اہل معرفت کا اتفاق ہے۔ جبکہ ایک گروہ اسے سچ سمجھتا ہے۔ یہ روایت محمد بن طاہر المقدسی نے نقل کی ہے۔وہ مسئلہ سماع میں اس روایت کو لیکر آیا ہے۔ اور ابو حفص سہروردی نے بھی اسے روایت کیا ہے؛ لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ: ’’میری ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صحابہ کے ساتھ اجتماع کے بارے میں نہیں ہے۔‘‘
یہ بات جو اس کے ذہن میں آئی ہے۔ دوسرے علماء کے ہاں یہ بات یقینی ہے ؛جو کہ اس کی دل میں آئی ہے۔ اور حدیث کا علم رکھنے والے ماہر اس بات پر متفق ہیں کہ یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹ گھڑ کر منسوب کی گئی ہے۔
اس سے بھی بڑھ کر [جھوٹ]ان لوگوں کا گمان ہے جو کہتے ہیں کہ : اہل صفہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی تھی۔ اور یہ کہ اولیاء کے لیے انبیائے کرام علیہم السلام کے ساتھ جنگ کرنا جائز ہے۔ جب کہ غدر ان کی طرف سے ہو۔ یہ روایت بہت بڑا کفر اور جھوٹ ہونے کے باوجود اس گروہ کے ہاں مروج ہے جو اپنے آپ کو احوال و معارف اور حقائق کی طرف منسوب کرتے ہیں ۔ درحقیقت ان لوگوں کے کچھ شیطانی احوال ہوتے ہیں ۔ اور جو شیاطین ان سے ملتے رہتے ہیں ؛ وہ انہیں بعض غیبی امور کے متعلق خبر دیتے ہیں ؛ اوران کے بعض کام کردیتے ہیں ۔ اورکچھ ضرورتیں پوری کردیتے ہیں ۔ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ یہ بہت بڑے اولیاء اللہ ہیں ۔ جب کہ وہ اولیاء شیطان ہوتے ہیں ۔
ایسے ہی کچھ احادیث ان لوگوں کے ہاں مروج اور مشہور ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت و الجماعت کی طرف منسوب کرتے ہیں ؛ اوروہ ان احادیث کو سنت خیال کرتے ہیں ؛ جبکہ وہ جھوٹ ہوتی ہیں ۔ جیسا کہ روزہ کے علاوہ فضائل عاشوراء محرم ؛اس دن سرمہ لگانے اور غسل کرنے ؛مہندی اورخضاب لگانے کی فضیلت ؛اور مصافحہ کے فضائل ؛اور اس دن میں جو اہل و عیال کے اخراجات میں وسعت دینے کی روایت ہے۔[یہ تمام روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہیں ]۔ عاشوراء کے دن روزہ کے علاوہ اس دن کی فضیلت کے بارے میں کوئی بھی صحیح روایت موجود نہیں ۔
ایسے ہی جو کچھ بعض متعین نمازوں کے بارے میں روایت کیا جاتا ہے؛ یہ تمام روایات باتفاق اہل علم من گھڑت اور جھوٹ ہیں ۔اور ائمہ حدیث میں سے کسی ایک نے بھی ان روایات کو اپنی کتابوں میں جگہ نہیں دی۔
ایسے ہی جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے اس روایت کے متعلق پوچھا کہ:’’جو کوئی عاشوراء کے دن اپنے اہل خانہ کے کھانے میں وسعت کرتا ہے ‘ اللہ تعالیٰ سارے سال کے لیے اس کے رزق میں وسعت پیدا کردیتے ہیں ۔تو آپ نے فرمایا : اس روایت کی کوئی اصل [بنیاد] ہی نہیں ہے۔‘‘
جیساکہ رجب کے روزوں کے بارے میں جو احادیث بیان کی جاتی ہیں اہل علم کے ہاں وہ تمام ضعیف ہی نہیں بلکہ جھوٹی ہیں ۔
ایسے ہی وہ روایات جو بطور خاص رجب کی فضیلت کے بارے میں نقل کی گئی ہیں ؛ یا پھر اس کے روزوں کے بارے میں ؛ یا رجب کے کسی ایک روزہ کے بارے میں ؛ یا مخصوص نماز کے بارے میں ؛جیسے [صلاۃ رغائب جو] رجب کے پہلے جمعہ کی رات کو پڑھی جاتی ہے؛ او رنصف شعبان کا الفیہ ؛ اور فضائل عاشوراء محرم کے بارے میں جو اہل و عیال کے اخراجات میں وسعت دینے کی روایت ہے؛ اور مصافحہ کے فضائل ؛ اورمہندی اورخضاب کے فضائل؛غسل وغیرہ کے فضائل ؛ عاشوراء کے دن کی نماز ۔ یہ تمام روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرمن گھڑت جھوٹ ہیں ۔
ایسے ہی جو کچھ ہفتہ وار نمازوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے: جیسے اتوار اور پیر کے دن کے علاوہ باقی ایام کی مخصوص نمازیں ؛ ایسی تمام روایات جھوٹ ہیں ۔ اور یہی حال نصف شعبان کا الفیہ ؛ اور رجب کے پہلے جمعہ کی نماز ۔ یا ستائیسویں شب کی نماز کے بارے میں تمام روایات من گھڑت اورجھوٹ ہیں ۔
یہی حال ان تمام نمازوں کا بھی ہے جن میں آیات کی تعداد یا سورتیں یاتسبیح متعین کی گئی ہے۔ ان کے جھوٹ ہونے پر تمام اہل علم محدثین کا اتفاق ہے۔سوائے نماز تسبیح کے۔ اس کے بارے میں دو قول ہیں ۔ ان میں سے بھی زیادہ ظاہر قول یہ ہے کہ یہ جھوٹ اور من گھڑت بات ہے۔اگرچہ اہل علم کا ایک گروہ اسے سچ سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان ائمہ میں سے کسی نے اس روایت کو قبول نہیں کیا۔ بلکہ احمد بن حنبل اور ائمہ صحابہ اس کو مکروہ سمجھتے تھے اور اس حدیث پر طعن کرتے تھے۔ امام مالک؛ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہم اللہ نے یہ حدیث مطلق طور پر سنی ہی نہیں ۔امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ کے اصحاب میں سے جن لوگوں نے اس کو مستحب کہا ہے وہ ان کا اپنا اختیاری کلام ہے؛ یہ ائمہ کرام سے منقول نہیں ہے۔
جہاں تک امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا تعلق ہے تو انہوں نے اس کو مشہور مذکور طریقہ کے مطابق مستحب نہیں سمجھا؛ جس میں قیام سے پہلے تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ بلکہ آپ نے اسے دوسرے مشروع او رمستحب طریقہ کے جائز کہا ہے۔ تاکہ کسی بھی سنت کی بنیاد کسی ایسی روایت پر نہ رکھی جائے جس کی کوئی اصل ہی ثابت نہ ہو۔
یہی حال تفسیر کی کتابوں کا بھی ہے ؛ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب بہت ساری چیزیں ایسی منقول ہیں جن کے بارے میں ماہرین علم حدیث یقینی طور پر کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا گیا ہے ۔ مثال کے طور پر ہر سورت کے فضائل کی احادیث جنہیں ثعلبی اور کلبی نے ہر تفسیر کے شروع میں اور ذکر کیا ہے؛ اور زمحشری ہر صورت کے آخر میں بیان کرتا ہے۔ اور محدثین یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سورتوں کے فضائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول چند احادیث ہی صحیح ہیں ۔ ان میں سے ایک وہ حدیث ہے جس میں سورت اخلاص کے فضائل بیان کیے گئے ہیں ؛اسے اہل صحاح نے روایت کیا ہے۔اور حافظ ابو محمد الخلال اور کچھ دوسرے حفاظ حضرات محدثین نے اس کے فضائل میں منفرد کتابیں تحریر کی ہیں ۔
وہ جانتے ہیں کہ وہ احادیث جو کہ سورت فاتحہ؛ آیت الکرسی؛ سورت بقرہ کی آخری آیات اورمعوذتین کے فضائل میں منقول احادیث صحیح احادیث ہیں ۔ اور اس تفریق کے لیے ان کے پاس وہ فرقان اور علم موجود ہے جس کی روشنی میں وہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کرتے ہیں ۔
جہاں تک احادیث اسباب نزول کا تعلق ہے؛ تو ان روایات کی اکثریت مرسل ہے؛ ان کی کوئی سند نہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں :’’تین قسم کے علوم ایسے ہیں جن کی کوئی سند نہیں ہوتی۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ ان کی کوئی اصل نہیں ہوتی: علم تفسیر؛ علم المغازی؛ اورعلم ملاحم ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تین قسم کے علوم میں مرسل احادیث ہوتی ہیں ۔
[مرسل روایات پر بحث:]
جہاں تک مرسل احادیث کا تعلق ہے تو ان کے قبول اور رد کے بارے میں اختلاف ہے۔ ان میں سے صحیح ترین قول یہ ہے کہ : مرسل روایات میں مقبول بھی ہوتی ہیں اور مردود بھی؛اور موقوف بھی۔پس جس کے بارے میں یہ معلوم ہوجائے کہ وہ صرف ثقہ سے ہی ارسال کرتا ہے؛ تواس کی مرسل روایت قبول کی جائے گی۔ اور جس کے بارے میں یہ پتہ چلے کہ وہ ثقہ اور غیر ثقہ ہر ایک سے ارسال کرتاہے: اور اس کی یہ مرسل روایت ایسی ہو جس میں مرسل عنہ کے حال کا پتہ نہ ہو تو یہ روایت موقوف ہوگی۔اوروہ مراسیل جو ثقہ راویوں کی روایات کے مخالف ہوں تو وہ مردود ہوں گی۔
جب مرسل دو طرح سے روایت کی گئی ہو؛ اور دونوں راویوں کے مشائخ کے مختلف ہوں ۔ تویہ اس روایت کی صداقت کی دلیل ہے۔اس لیے کہ عمومی طور پر ایک جیسی غلطی میں تماثل یہ عمداً جھوٹ بولنا تصور نہیں کیا جاسکتا۔تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت سچ ہے۔ اس لیے کہ خبر دینے والے پر جھوٹ کا امکان دو طرح سے ہوسکتا ہے؛ یا تو وہ جان بوجھ کر جھوٹ بول رہا ہے؛ یا پھر اس سے غلطی کا ارتکاب ہورہا ہے۔پس جب قصہ ایسا ہو جس کے بارے میں یہ معلوم ہوکہ یہ دونوں خبر دینے والے آپس میں ایک جگہ پر جمع نہیں ہوئے۔ اور عادتاً ان دونوں کے مابین جھوٹ میں تماثل عمداً یا خطا سے محال ہو۔ مثال کے طور پر ایک لمبا قصہ ہو؛ اور اس میں بہت سارے اقوال ہوں ۔ اور ان میں سے دوسرا راوی بالکل ایسے ہی روایت کررہا ہو جیسے پہلے راوی نے بیان کیا ہے؛ تواس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خبر سچی ہے۔
یہ وہ طریقہ ہے جس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت بھی معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ان دونوں نبیوں نے اللہ تعالیٰ ؛ اس کے رسولوں ؛ اوراس کی تخلیق عالم؛ حضرت آدم اور حضرت یوسف علیہماالسلام کے قصے:اور ان کے علاوہ دوسرے انبیائے کرام علیہم السلام کے قصے۔بالکل جیسے ایک پیغمبر علیہ السلام نے بتایا ؛ دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں ویسے ہی خبر دی ۔ حالانکہ انہوں نے ایک دوسرے سے استفادہ نہیں کیا۔ اور عادتاً ایسی دوباطل خبروں کا متماثل ہونا محال ہوتا ہے۔ اس لیے کہ بلا شک و شبہ جو کوئی لمبے اورمتعین تفصیلی احوال کی خبر انتہائی باریک بینی سے دیتا ہے؛ تو اگروہ اس خبرکے دینے میں جھوٹا ہو تو اس کی خبر میں اختلاف پایا جائے۔ اس لیے کہ جھوٹ بولنے والے کا ایک لمبے واقعہ کی تفصیل بغیر کسی اختلاف کے بیان کرنا ممتنع ہے۔ خصوصاً ان امور میں جن کی طرف عقل ہدایت پاتی ہے۔بلکہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ دونوں خبر دینے والوں نے علم پر مبنی سچی خبر دی ہے۔
لوگوں کے احوال اسی طریقہ سے معلوم ہوتے ہیں ۔ پس اگر کوئی انسان کسی دوسرے شہر سے آتا ہے اور وہ وہاں پر پیش آنے والے کچھ واقعات کے بارے میں تفصیلی خبردیتا ہے۔جس میں مختلف قسم کے اقوال و افعال کو انتہائی منتظم انداز میں بیان کرتا ہے۔ پھرایک دوسرا آدمی آتا ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان دونوں کا جھوٹ پر اتفاق نہیں ہے؛ اور پھر وہ بھی پہلے آدمی کی طرح خبر دیتا ہے۔ تو اس سے قطعی طور پر یقینی علم حاصل ہوجاتا ہے کہ واقعہ بالکل ایسے ہی پیش آیا ہے۔ اس لیے کہ ایسے واقعات میں کبھی کبھار جھوٹ بھی سامنے اس وقت آتا ہے جب دونوں کا جھوٹ پر اتفاق ہوا ہو؛ اور وہ انہوں نے یہ معلومات ایک دوسرے سے حاصل کی ہوں ۔جس طرح کہ اہل باطل ؛ باطل عقائد ایک دوسرے سے وراثت میں نقل کرتے چلے جاتے ہیں ؛ جیسے نصاری ؛ جہمیہ اور رافضہ؛ اور ان کی مانند کے دوسرے لوگ۔ اس میں کوئی شک نہیں اگرچہ ان کا باطل ہونا عقلی ضرورت کے تحت معلوم ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہ ایک دوسرے سے ایسے ہی نقل کرتے چلے جاتے ہیں ۔ جب اس پر ان کی آپس میں ایک دوسرے سے موافقت ہے تو ان کا باطل پر اجماع بھی جائز ٹھہرا۔
بہت ساری جماعتیں ایسی ہیں جن کا علی سبیل التواطؤ [بطور اتفاق ] ضروریات کے انکار پر اتفاق جائز ہے؛ خواہ ایسا عمداً جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہو یا پھر عقیدہ میں خطا کی وجہ سے ہو۔ جب کہ اس سے کم دوسری ضروریات کے انکار پر ان کا اتفاق ممتنع ہے۔