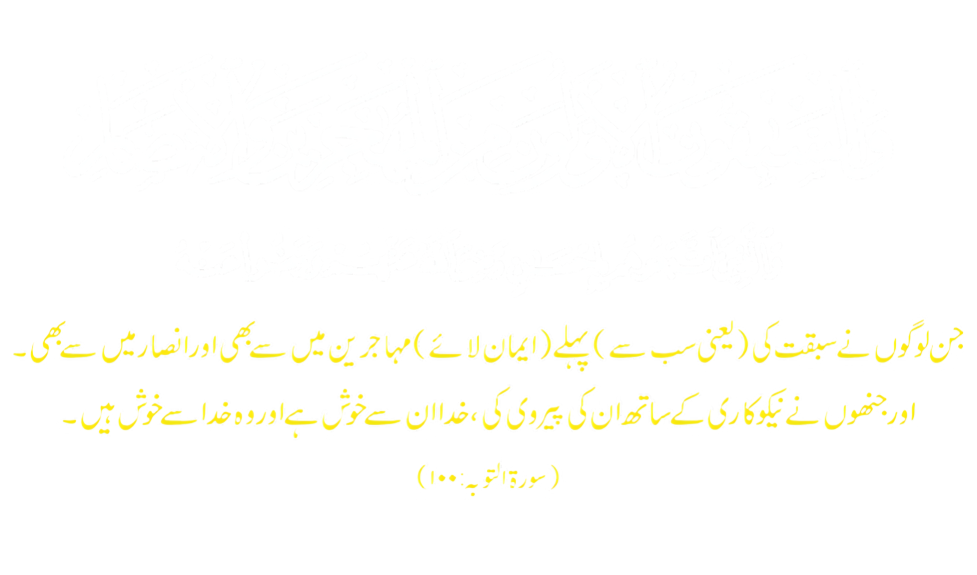فلاسفہ اور دیگر ملتوں کے ائمہ کا متکلمین پر رد
امام ابنِ تیمیہؒفلاسفہ اور دیگر ملتوں کے آئمہ کا متکلمین پر رد
متکلمین کہتے ہیں : اس سے توجسم کا حدوث ثابت ہوتا ہے ۔کیونکہ جسم حوادث سے خالی نہیں ہوتا۔ اور جو بھی چیز حوادث سے خالی نہ ہوتو وہ خود بھی حادث ہوتی ہے۔ اور ان لوگوں نے ان اشیاء کے درمیان جو نوعِ حوادث سے خالی نہیں ہوتی اور ان اشیاء کے درمیانِ جو عینِ حوادث سے خالی نہیں ہوتی ؛کوئی فرق نہیں کیا ۔ اور نہ ہی انہوں نے حوادث کے باب میں ان حوادث کے درمیان جو کہ خود مفعول اور معمول بنیں کسی علت کے لیے یا یہ کہ کسی مفعول کے لیے وہ خود فاعل بنیں ؛ اور بذاتِ خود واجب ہو،اس میں کوئی فرق نہیں کیا۔پس ان متکلمین سے فلاسفہ اور دیگر ملتوں کے آئمہ نے کہا ہے کہ: یہ دلیل جس سے تم نے عالم کا حدو ث ثابت کیاہے؛حقیقت میں یہ دلیل تو عالم کے حدوث کے ممتنع ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ اور جو کچھ تم نے ذکر کیا ہے وہ تو اس بات کی نقیض پر دلالت کرتا ہے جس کوتم ثابت کرنا چاہتے ہو۔اس کی وجہ یہ ہے کہ حادث جب ایک بار عدم سے وجود میں آیا تو یہ ضروری ہے کہ وہ ممکن ہو۔اور امکان کے لیے کوئی خاص متعین وقت ثابت نہیں ۔پس جوبھی وقت فرض کرلیا جائے؛امکان اس سے پہلے ثابت ہوگا ۔پس فعل کے امکان اور اس کے جواز اور صحت کے لیے کوئی ایسا مبدأ ثابت نہیں جس کی کوئی منتہی ہو۔ پس اس سے لازم آتا ہے کہ فعل ازل سے ممکن اورجائز اور صحیح تھا۔اور اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ازل سے قادر تھا۔اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایسے حوادث کا وجود ممکن ماننا پڑے گا جن کے اول کے لیے کوئی منتہیٰ نہیں ؛ یعنی وہ ازل سے ہیں ۔
جہمیہ ، معتزلہ اور ان کے وہ متبعین جو متکلمین میں سے ہیں ان کی طرف سے مناظر نے کہا کہ:’’ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ حوادث کے امکان کے لیے کوئی ابتداء نہیں یعنی وہ ازل سے ہیں ۔ البتہ ہم کہتے ہیں کہ :’’حوادث کا امکان اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ مسبوق بالعدم ہوتے ہیں جس کے لیے کوئی بدایت اور شروع نہیں ۔اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک حوادث کا اپنی نوع کے اعتبار سے قدیم ہونا ممتنع ہے۔ بلکہ اس کے نوع کا حادث ہونا ضروری ہے لیکن کسی معین وقت میں اس کا حدوث معین نہیں ۔ پس حوادث کا ممکن ہونا اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ ایسے مسبوق بالعدم ہیں جن کے لیے کوئی اول نہیں بخلافِ جنسِ حوادث کے۔
تو ان کے جواب میں کہا جائے گا کہ: فرض کر لو تم یہ بات کہتے ہو۔ لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمہارے نزدیک جنسِ حوادث کے امکان کے لیے ایک ابتداء ہے۔ پس یقیناً جس طرح حدوث تمہارے نزدیک نا ممکن ہونے کے بعد ممکن بن گیا ؛ اور اس امکان کے لیے کوئی معین وقت نہیں ؛بلکہ کوئی بھی وقت فرض کر لیا جائے۔ تو امکان اس سے پہلے ثابت ہوتا ہے۔ اس کے نتیجہ میں لازم آتا ہے کہ امکان کو دائمی ماننا پڑ ے گا ورنہ لازم آئے گا کہ بغیر کسی چیز کے حدوث کے اور بغیر کسی نئے حال کے تجدد کے جنس حوادث امکان سے امتناع کی طرف بدل گئے۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ بغیر کسی سبب کے تجدد کے جنسِ حدوث یا جنسِ حوادث یا جنسِ فعل یا جنسِ احداث ( یااس کے مشابہ جو دیگر عبارات ہیں )کی حقیقت کا امتناع سے امکان کی طرف بدل جانا (حالانکہ وہ پہلے ممتنع تھا )؛عقل کے صریح فیصلے کے مطابق ممتنع ہے۔ اور یہ اس بات کو بھی مستلزم ہے کہ کوئی جنس امتناعِ ذاتی سے امکانِ ذاتی کی طرف بدل جائے۔ کیونکہ یقیناً ان کے نزدیک جنسِ حوادث کی ذات ممتنع ہونے کے بعد ممکن بن جاتی ہے۔ اور یہ انقلاب کسی وقتِ معین کے ساتھ خاص نہیں اس لیے کہ یقیناً کسی بھی وقت کو اگر فرض کر لیا جائے گا تو امکان اس سے پہلے ثابت ہوگا لہٰذا لازم آیا کہ یہ حقیقت کا انقلاب امتناع سے امکان کی طرف ازل سے ثابت ہے جو اس بات کو مستلزم ہے کہ ممتنع ازل سے ممکن ہی تھا۔
اور یہ بات امتناع کے اعتبار سے زیادہ ابلغ اور عقلی اعتبار سے زیادہ ناجائز ہے ہمارے اس قول سے کہ حادث ازل سے ممکن ہے پس تحقیق جس مقصد اور جس نتیجہ سے یہ بھاگنا چاہتے تھے ان پر اس سے زیادہ شنیع اور فساد کے اعتبار سے زیادہ اشد بات کا الزام آگیا اس لیے کہ یقیناً یہ بات عقلا سمجھ میں آتی ہے کہ حادث ممکن ہے اور یہ بات بھی عقلا سمجھ میں آتی ہے کہ یہ امکان ازل سے ہے ۔رہا ممتنع کا ممکن بننا ؛تو وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ممتنع ہے۔ پس یہ کہنا کیسے درست ہوگا کہ اس ممتنع کا امکان ازل سے ہے اور یہ بھی کہ جو شرط انہوں نے ذکر کی ہے کہ جنسِ فعل یا جنسِ حوادث کا ازل سے امکان اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ مسبوق بالعدم ہو ں ؛تو یہ شرط جمع بین النقیضین کو مستلزم ہے۔ اس لیے کہ اس کا ازل سے ہونے کا تقاضا ہے کہ اس کے امکان کے لیے کوئی ابتداء اور شروع نہیں اور اس کا امکان قدیم اور ازلی ہواور اس کا مسبوق بالعدم ہونے کا تقاضا ہے کہ اس کے لیے کوئی ابتداء ہے جو کہ قدیم اور ازلی نہیں ۔ پس ان کا یہ قول اس بات کو مستلزم ہوا کہ حوادث کے لیے کوئی ابتداء ثابت ہوناضروری ہو۔اور یہ بھی کہ ضروری نہیں ۔ بے شک انہوں نے ایک ایسی بات فرض کی ہے جو ممتنع ہے اور جو ممتنع تقدیر ہو تو تحقیق اس کے نتیجے میں حکمِ ممتنع ہی لازم آتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:
﴿ لَوْ کَانَ فِیْہِمَا اٰلِہَۃٌ اِلَّا اللّٰہُ لَفَسَدَتَا﴾ [الانبیاء ۲۲]
’’ اگر زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود ہوتا تو ان دونوں میں فساد پیدا ہوجاتا۔‘‘
پس بے شک ان لوگوں کا قول یعنی جنس حوادث کے امکان[اس شرط پر کہ وہ مسبوق بالعدم ہوں ]کے لیے کوئی ابتداء نہیں اس بات کومتضمن ہے کہ جس چیز کے لیے ابتداء ثابت ہے اسی کے لیے ابتداء ثابت نہ ہو اس لیے کہ جو چیز بھی مسبوق بالعدم ہونے کے ساتھ مشروط ہو اس کے لیے ابتداء ہوتی ہے اور اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اس کے لیے کوئی ابتداء نہیں یہ تو جمع بین النقیضین ہوا۔
اور یہ بھی کہا جائے گاکہ یہ ایک ایسی تقدیر ہے کہ خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں پس یہ کسی قائل کے اس قول کے بمنزلہ ہو اکہ کیا جنسِ حوادث کے امکان کے لیے کوئی انتہا ہے حالانکہ وہ مسبوق بالعدم بھی ہیں ؟یا ان کے امکان کے لیے کوئی انتہا نہیں ؟ پس جیسے کہ یہ بات جمع بین النقیضین کو مسلتزم ہے تو مأل کار کے طور پر تمہاری بات ابتداء میں جمع بین النقیضین کو مستلز م ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کسی بھی ممکن کے دو طرفین [وجود وعدم ]میں سے ایک جانب کو ترجیح تب حاصل ہوتی ہے جب کوئی مرجحِ تام پائے جائے جس کی وجہ سے ممکن کو وجود ملے۔ اور بتحقیق یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے دو طرفین میں سے ایک کو ترجیح نہیں ہوگی یعنی وجود میں عدم پر مگر کسی ایسے مرجح تام کے ذریعے کہ جو اس ممکن کے وجود کو مستلزم ہو اور یہ دوسرا قول نسبتاً زیادہ درست ہے ۔جیسے کہ یہ ثابت ماننے والے مناظرین اسلام کا مسلک ہے۔کیونکہ یقیناً ممکن کے لیے حالتِ عدم میں بقاء ثابت کرنا کسی مرجح کی طرف محتاج نہیں ہے۔ اور جس نے کہا کہ یہ کسی مرجح کی طرف محتاج ہے؛ تو اس نے کہا کہ اس کے لیے کسی مرجح کا نہ پایا جانا ہی اس کے عدم کو مستلزم ہے۔ لیکن اس پر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ یہ تو اس کے عدم کے لیے مستلزم ہوا یہ نہیں کہ بعینہ یہ عدم ہی وہ امر ہے جو اس کے عدم اور ناپید ہونے کے لیے مُوجب ہے اور نفسِ الامر میں اس سے اس کا عدم واجب اور ضروری نہیں ہو جاتا بلکہ نفس الامر میں معدوم اور نا پید ہونے کے لیے تو کوئی علت درکار ہی نہیں کیونکہ یقیناً معلول کا عدم علت کے عدم کو مستلز م ہوتا ہے یعنی جب معلول نہیں پایا جائے گا تو یہ لازم ہے کہ علت بھی نہیں پائی جائے گی اور ملزوم علت بننے سے اعم ہے کیونکہ وہ مرجحِ تام اگر ممکن کے وجو د کو مستلزم نہ ہو تو پھر ممکن کا وجود اس مرجحِ تام کے ساتھ جائز بنے گا نہ کہ واجب یاممتنع اور پھر ایسی صورت میں وہ ممکن ہی بنے گا پس وہ موقوف ہوگا کسی مرجح پر کیونکہ بے شک ممکن وہ صرف اورصرف مرجح کے نتیجے سے وجود میں آتاہے یعنی جو اس کے دو طرفین [وجود اور عدم ]میں سے وجود کو ترجیح دے۔
پس یہ بات اس پر دال ہے کہ اگر کسی ممکن کے لیے ایسا مرجح حاصل نہ ہو جو اس کے وجود کو مسلتزم ہو تو پھر اس کا وجود ممتنع ہے اور جب تک اس کا وجود ممکن اور جائز ہو گایعنی غیر لازم ہو گاتو وہ وجود میں نہیں آئیگا اور یہی وہ بات ہے جس کے قائل اہلِ سنت کے وہ آئمہ ہیں جو قدر کا اثبات کرتے ہیں اور اس بات فلاسفہ کے آئمہ نے ان کی موافقت بھی کرتے ہیں اور یہ وہ امر ہے کہ جس کے ذریعے انہوں نے اس بات پراستدلال کیا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کے خالق ہیں ۔
کامل قدرت اور یقینی ارادہ فعل کے وجود کا تقاضا کرتی ہے:
معتزلہ میں سے قدریہ اور ان کے علاوہ دیگر لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ قادر ذات کے لیے یہ بات ممکن ہے کہ فعل کو ترک پر ترجیح دے؛ بغیر اس کے کہ کوئی ایسا کوئی امر پایا جائے جو فعل کو مستلزم ہو۔ اور انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ اگر وہ ذات اس طور پر قادر نہیں تو لازم آئے گا کہ وہ مُوجِب بالذات ہیں قادر نہیں ہیں ۔ وہ کہتے ہیں کہ: قادر ذات تو اس مختار ذات کو کہتے ہیں کہ جوجب چاہے تو کرے اور چاہے تو چھوڑ دے ۔پس جب یہ کہا جائے کہ اس پر لازم کئے بغیر کوئی فعل صادر نہیں کرتا[یعنی فعل کے کرنے کا کوئی مسلتزم پایا جائے] تو پھر وہ مختار نہ رہا بلکہ مجبور ہوا۔
تو جمہور اہل ملت نے اس کے جواب میں کہا کہ: بلکہ یہ تو خطاہے اس لیے کہ یقیناً وہ قادر ذات کہ جو اگر چاہے تو کرے اور چاہے تو چھوڑ دے ۔یہ وہ ذات نہیں ہے کہ اگر فعل کا پکا ارادہ کرے اور وہ اس پر قدرتِ تامہ کے ساتھ قادر ہو تو وہ فعل ممکن اور جائز رہے گا نہ کہ لازم اور واجب اور نہی ممتنع اور محال۔
بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بات یقیناً معلوم ہے کہ وہ ذات جو قادرِ مختار ہے جب ارادہ کرتا ہے کسی فعل کا پکے ارادے کے ساتھ اس حال میں کہ وہ اس پر قدرتِ تامہ کے ساتھ قادربھی ہو؛تو اس سے فعل کا وجود لازم آجاتا ہے۔ اور وہ فعل واجب لغیرہ بن جاتا ہے نہ کہ واجب لنفسہ؛ جیسا کہ اہل اسلام یہ کہتے ہیں کہ: جو کچھ اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں تو اس پر وہ قادر ہیں ۔ پس وہ جب کسی چیز کو چاہیں گے تو اس کی مراد حاصل ہوگی؛ اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اس پر قدر ت ہوگی؛ پس اس کا وجود لازم ہوگا ۔اور جس کو وہ نہیں چاہے گا وہ موجود نہیں ہوگا پس یقیناً اس نے اس کا ارادہ نہیں کیا؛ اگرچہ وہ اس پر قادر ہے۔ لیکن اس کے وجود کے لیے ایسا مقتضی نہیں پایا گیا جو اس کو عدم سے وجود میں لے آئے پس ایسے حال میں اس کا وجود جائز نہیں ۔
اہل اسلام کہتے ہیں : قدرتِ تامہ اور ارادہ جازمہ کے ساتھ عدمِ فعل ممتنع ہے۔ اور کسی فعل کا نہ پایا جانا صرف اسی صورت میں متصور نہیں ہو سکتا کہ یا تو اس پر کامل قدرت حاصل نہیں ہے یااس کے کرنے کا کامل ارادہ نہیں ہے ۔ اورایسی چیز تو انسان اپنی ذات میں بھی پاتا ہے اوریہ یقینی دلائل کے ساتھ معروف اور معلوم ہے۔
کیونکہ ایک مختار ذات کا فعل صرف اور صرف اس کی قدرت اور ارادے پر موقوف ہوتاہے۔بے شک وہ کبھی اس پر قادر ہوتا ہے لیکن فعل کا ارادہ نہیں کرتا پس وہ اسے کرتا نہیں اور کبھی فعل کا ارادہ تو رکھتا ہے لیکن وہ اس سے عاجز ہونے کی وجہ سے نہیں کر پاتا۔جب کہ کمال قدرت بھی ہو اور ارادہبھی جازمہ(پختہ ) ہو تو فعل کا وجود اس کے علاوہ کسی اور چیز پر موقوف نہیں ہوتا۔پس کامل قدرت اور پکا ارادہ ہی کسی ممکن فعل کا مرجحِ تام ہے۔ پس ان دونوں چیزوں کے پائے جانے کے وقت اس فعل کا وجود لازم اور واجب ہوجاتا ہے۔ اور رب تعالیٰ تو ایسے قادرِ مختار ہیں جو اپنی مشیت کے ساتھ فعل صادر کرتے ہیں اس پر کوئی جبرو اکراہ کرنے والا نہیں اور نہ ہی وہ اپنی ذات کے اعتبار سے کسی فعل کے لیے مُوجِب بنتا ہے۔ اور نہ اس معنی پر کہ وہ ایسی ذات کے ذریعے فعل صادر کرتا ہے جس کے لیے کوئی مشیت اور قدرت ثابت نہیں ۔ بلکہ جس فعل کا وجود وہ چاہتا ہے؛ تو وہ اپنی مشیت اور قدرت کے ذریعے فعل کو وجود بخشتا ہے۔ یہ اس ذات کی حقیقت ہے جو کامل قدرت اور کامل اختیار والی ہو۔ پس وہ ایسا قادر مختار ہے جو اپنی مشیت سے ان تمام چیزوں کو وجود دیتا ہیجن کو وہ وجود دینا چاہے ۔
اور اس تحریر کے ذریعے اس مسئلہ میں وارد ہونے والا اشکال زائل ہوگیا۔ اس لیے کہ جب موجب بذاتہ ازلی ہو تو اس کا موجب بھی اس کے ساتھ ملاہوا ہوتا ہے۔ پس جب رب سبحانہ و تعالیٰ ازل سے ہی اس عالم کے لیے موجب بذاتہ ہے توجو کچھ اس کائنات میں ہے ؛ وہ بھی ازل کے ساتھ اس سے مقارن ہوا۔اور ایسا کہنا تو ممتنع ہے۔ بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیئت میں تھا وہ موجود تھا ا ور جو کچھ اس کی مشیئت میں نہیں تھا؛ وہ نہیں تھا۔ [یعنیجس چیز کے وجود کو اللہ تعالیٰ چاہیں وہ موجود ہو جاتا ہے اور جس کے عدم کو چاہیں تو وہ معدوم رہتا ہے] پس عالم میں سے وہ تمام چیزیں جن کے وجود کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ان کا وجوداللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت کے تحت ہونا واجب ہوتاہے۔ اور جسے نہیں چاہتا تو اس کا وجود ممتنع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جو چیز بھی عدم سے وجود میں آتی ہے تواس کی قدرت اور مشیت کے ہی ہوتی ہے۔ اور یہ بات اس کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ تمام اشیاء جن کے وجود کا اللہ تعالیٰ ارادہ کریں ان کا وجود واجب ہے۔[ یعنی یہ ممتنع ہے کہ وہ وجود میں نہ آئے] ۔
[موجب بالذات ؟]
’’مُوجِب بالذات ‘‘کے لفظ میں اجمال ہے۔ اگر اس سے یہ مراد لیا جائے کہ وہ ان تمام اشیاء کو وجود دیتا ہے جن کو اپنی مشیت اور قدرت کے ذریعے وہ ایجاد کر تا ہے؛ تو اللہ تعالیٰ کے فاعل بالقدرت و مشیئت ہونے اور موجوب بالذات ہونے میں اس تفسیر کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں رہتا۔ اور اگر مُوجِب بالذات کے لفظ سے یہ مراد لیا جائے کہ وہ اشیاء کو ایک ایسی ذات کے ذریعے موجود کر دیتا ہے جو قدرت اور اختیار سے خالی ہے تویہ بات باطل اور ممتنع ہے۔ اور اگر یہ مراد لیا جائے کہ اس کی ذات ایسی علتِ تامہ ازلیہ ہے جو اپنے ازلی معلول کو مستلزم ہے؛ اس طور پر کہ اس عالم میں سے بعض اشیاء جیسے فلک اور دیگر بعض اجسام جن کی رائے کے مطابق قدیم ہیں اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ اور اس کی ذات کے لیے ازل سے ابد تک لازم ہیں ؛ تویہ بھی باطل ہے۔
پس لفظ مُوجِب بالذات کی اگر ایسی تفسیر کی جائے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عالم میں سے کسی چیز کے قدیم ہونے کا تقاضا کرے ؛ یا اس کی ایسی تفسیر کی جائے جو اللہ تعالیٰ سے صفاتِ کمال کے سلب کا تقاضا کرے تو وہ باطل ہے۔ اور اگر اس کی تفسیر ایسے الفاظ سے کی جائے جو اس بات کا تقاضا کرے کہ : اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہیں وہ ہو جاتا ہے اور جو نہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔ تو یہ مراد برحق ہے۔ اس لیے کہ یقیناً جس چیز کے وجود کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں پس تحقیق اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت کے تحت اس کا وجود واجب ہوا۔ لیکن یہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ اس اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سے ازل ہی میں کسی معین چیز کا ارادہ کیا تھا۔ بلکہ اس کاازل ہی میں کسی شے معین کے وجود کاارادہ کرنا کئی وجوہ کی بناء پر ممتنع ہے ۔
اسی وجہ سے تو اکثرعقلائے فلاسفہ اس بات کے قائل ہیں کہ کوئی بھی ازلی چیز کسی دوسری ذات کے لیے مراد اور مقدور نہیں بن سکتی ۔اورمتکلمین مناظرین حضرات کے درمیان اس بات میں ہمیں کوئی اختلاف معلوم نہیں ہوسکا کہ اللہ تعالی کی جو صفات ازلی اور اس کے ذات کے ساتھ لازم ہیں ان میں کوئی بھی صفت وجود کے اعتبار سے اس کی ذات کے موخر نہیں ۔ اور یہ بھی جائز نہیں کہ اس کی کوئی صفت اور مراد اور مقدور بن جائے۔ اور اس بات میں بھی کسی کا اختلاف نہیں کہ جو چیز مراد اور مقدور ہوتی ہے یعنی کوئی دوسری ذات اس کا ارادہ کرتی ہے تو اس کو وجود دے دیتی ہے تو اس کو قدرت حاصل ہوتی ہے تو وہ صرف اور صرف حادث ہی ہوتا ہے جو کہ تھوڑا تھوڑا کر کے وجود میں آتا ہے اگرچہ وہ اپنی نوع کے اعتبار سے ازل سے موجود ہو؛ یا اس کی پوری نوع ہی عدم کے بعد وجو دمیں آئی ہو۔
اسی وجہ سے وہ لوگ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن قدیم اوراللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ لازم ہے؛ وہ تمام لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت کے ذریعے متکلم نہیں ۔اور اس کی مشیت اور قدرت کے ذریعہ بندہ میں اس قدیم صفت کا ادراک پیدا کرنا ہے۔ اور وہ لوگ جنھوں نے یہ کہا کہ اللہ کا کلام تو قدیم ہے۔ اور انھو ں نے اس سے یہ مراد لی ہے کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے قدیم ہے؛ وہ اس بات پر متفق ہیں کہ وہ اپنی مشیت اور قدرت سے متکلم نہیں ۔ خواہ وہ یہ کہیں کہ کلام ایک ہی صفت ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے یا وہ یہ کہیں کہ کلام حروف ہیں ؛ یا حروف اور ایسی اصواتِ قدیمہ ہیں جو اپنی عین کے اعتبار سے ازلی ہوں ۔
بخلاف ان آئمہ سلف کے جنھوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت اور قدرت سے متکلم ہیں ۔اوربلاشبہ وہ ازل ہی سے متکلم ہیں جب بھی چاہیں جیسے چاہیں ۔ پس یقیناً یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ صفتِ کلام اپنی نو ع کے اعتبار سے تو قدیم ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ کے کلمات کے لیے کوئی انتہاء نہیں ۔ بلکہ وہ ازل سے اپنی مشیت اور قدرت سے متکلم ہیں ۔ اور ازل ہی سے ہی جیسے چاہیں جب چاہیں متکلم ہیں ۔اور اس جیسی دیگر عبارات بھی ہیں ۔ اور وہ لوگ جنھوں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت اور قدرت سے متکلم ہیں ؛ اور اس کا کلام غیر کے اعتبار سے حادث اور اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے؛ یا یہ کہا کہ اس کا کلام ایسی مخلوق ہے جو اس کی ذات سے جدا ہے؛ تو ان لوگوں کی رائے کے مطابق یہ بات ممتنع ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم بن جائے۔
پس تحقیق عقلاء کے تمام گروہ اس بات پر متفق ہیں کہ ایسی معین قدیم اور ازلی ذات جو واجب لذاتہ ہو وہ کسی دوسرے کے لیے مقدور اور مراد نہیں بنتی۔ بخلاف اس کے کہ جس کی نوع تو ازل سے موجود تھی لیکن اس سے تھوڑا تھوڑا کر کے وجود ملا۔[ یعنی وہ چیز دھیرے دھیرے وجود میں آئی]۔ تو یہی رائے اہل سنت والحدیث اسلاف کے آئمہ کی بھی ہے یعنی کے بے شک وہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت اور قدرت سے متکلم ہیں ۔ جیسے کہ ان جمہورِ فلاسفہ کی رائے ہے جو افلاک اور دیگر مخلوقات کے حدوث کے قائل ہیں جن میں سے ارسطو اور اس کے اصحاب بھی ہیں ؛ جو افلا ک کے قدیم ہونے کے قائل ہیں ۔
پس ائمہ اہل ملت اور ائمہ فلاسفہ اس بات کے قائل ہیں کہ افلاک حادث ہیں جوکہ عدم سے وجودمیں آئے ہیں ۔ باوجود یہ کہ وہ اسکے بھی قائل ہیں کہ نوعمقدورومراد ازل سے موجود ہے جو کہ آہستہ آہستہ وجو دمیں آئی۔ لیکن متکلمین میں سے بڑی تعداد اس بات کی قائل ہے کہ جو بھی چیز دوسری چیز کے لیے مقدور اور اس کی مراد ہو تو یہ بات ممتنع ہے کہ وہ ازل سے موجود ہو اور دھیرے دھیرے وجو د میں آئے اور ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جو مستقبل میں بھی اس بات کے ممتنع ہونے کے قائل ہیں ۔ اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ ان فلاسفہ نے دلائل بازی کی جوقدمِ عالم کے قائل ہیں ۔ اور جب انہوں نے ان کے ساتھ مناظرہ کیا ؛ توان کا اعتقادہوگیا کہ انھو ں نے ان کو دلائل میں مغلوب کر دیاہے۔اب تو یہ سمجھنے لگے کہ انھو ں نے تمام اہل ملت کو شکست دے دی۔ حالانکہ ان کو دیگر ملتوں کے آئمہ اور قدیم فلاسفہ کے بڑے بڑے آئمہ کے اقوال کا علم ہی نہیں ۔ اور اس کا سبب اِن کا یہ ظنِ فاسد ہے کہ دیگر ملتوں کے آئمہ اور فلاسفہ کا صرف اور صرف وہی قول ہے جو متکلمین کا ہے یا مجوس اور فرقہ حرَّانیہ کا ہے۔[یہاں پر مجوس سے ابن تیمیہ کی مراد وہ معتزلہ ہیں جو کہتے ہیں کہ: (خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور شر انسان کی طرف سے ہوتا ہے)۔اور حیرانیہ سے ان کا مقصود اسلام کی طرف منسوب فلاسفہ ہیں ؛ خاص کر فاریابی ؛ جس نے فلسفہ حیران کے مشرکین صابیہ سے شہر حیران میں سیکھا تھا۔ دیکھیں : الرد علی المنطقیین ۸۷۹۔] یا ان لوگوں کا قول جو کسی معین مادے کے قدم کے قائل ہیں ؛ یا اس طرح کے دیگر وہ اقوال جن کا فساد اہلِ نظر کے ہاں واضح ہے ؛ اس کو ایک اور جگہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ۔
یہاں تومقصود صرف اتنی بات ہے کہ عام عقلاء اس بات پر متفق ہیں کہ کسی معین چیزکے مراد(جس کا ارادہ کیا جائے ) اور مقدور ہونے پر علم اُس کے حادث ہونے پر علم حاصل ہونے کو مستلزم ہے حالانکہ اس سے پہلے وہ معدوم تھا۔ بلکہ یہ بات تو عقلاء کے نزدیک بداہۃ ضرورت کے تحت معلوم ہے۔یہی وجہ ہے کہ مناطقہ کے نزدیک تو کسی چیز کے بارے میں یہ تصور کرناکہ وہ کسی فاعل کا مقدور ہے اور فاعل اس کا ارادہ رکھتاہے ؛اور اس فاعل نے اپنی مشیت اور قدرت سے اس کام سرانجام دے چکا ہے؛ یااس شے کو وجود دیا ہے ، اس شے کے محدث ہونے کو مستلزم ہے۔بلکہ ان کے نزدیک تو کسی چیز کے بارے میں صرف مفعول یا مخلوق یا مصنوع ہونے کا تصور ہی اس کے حادث ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ یعنی یہ کہ وہ عدم سے وجود میں آیا۔ پھر اس کے بعد کبھی کبھاریہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس فاعل نے اپنی مشیت اور قدرت سے اس کام کو کیا ہے یا نہیں ؟اور جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ کوئی بھی فاعل فاعل نہیں بنتا مگر صرف اور صرف اپنی مشیت اورقدرت کے سے اپنی مقدور اور مرادچیز کو انجام دے؛ جب وہ انجام دے تو وہ چیز محدث ہوتی ہے۔یہ اس بات پر ایک دوسری دلیل بن گئی کہ وہ شے محدث ہے۔ اسی وجہ سے عقلاء میں سے جس نے بھی اس بات کا تصور کیاہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے یا اشیاء میں سے کسی شے کو پیدا کیا ہے تو یہ بات اس کو مستلزم ہے کہ وہ مخلوق بھی محدث ہے ؛ اورعدم سے وجود میں آئی ہے۔
اور جب ان میں سے بعض سے یہ کہا جائے کہ یہ بتلاؤکہ وہ قدیمِ مخلوق ہے یا قدیمِ محدث ہے۔ مخلوق اور محدث کے لفظ سے وہ معنی مراد تھے جو ان متأخرین دہری فلاسفہ بیان کرتے ہیں ۔ جو محدث کو معلول بتاتے ہیں ۔ اور اس بات کے قائل ہیں کہ وہ قدیم اور ازلی ہے؛ اس کے باوجود وہ ایسا معلول اور ممکن ہے جو وجود اور عدم دونوں کو قبول کرتا ہے۔ پس جب عقلِ سلیم اس مذہب کا تصور کرتا ہے تو یقیناً اس پر تناقض کا حکم لگاتا ہے۔ اور یہ بھی جان لیتا ہے کہ اس مذہب کے قائلین نے تونقیضین کو جمع کر لیا ہے۔کیونکہ جب انہو ں نے ایک ایسی مخلوق کو مان لیا جوکہ محدث اورمعلول اور مفعول ہو اور وجود اور عدم کا امکان رکھتا ہو؛ اور ان تمام صفات کے باوجود انہوں نے اس ذات کوقدیم اور ازلی بھی فرض کر لیا ہے جوکہ واجب الوجوب لغیرہ ہے اور اس کا عدم توممتنع ہے ۔
ہم نے اس بات کو نسبتاً زیادہ تفصیل کے ساتھ محصل اور غیر محصل پر کلام کرتے ہوئے بیان کیا ہے اور وہاں ہم نے یہ بات بتلائی ہے کہ امام رازی رحمہ اللہ‘[ابو عبداللہ محمد بن عمر بن الحسن الحسین الرازی : فخر الدین ؛المعروف بابن الخطیب؛ متوفی ۶۰۶ہجری۔ ان ائمہ اشاعرہ میں سے ایک تھے جنہوں نے اشعری مذہب کے ساتھ فلسفہ اور اعتزال کو ملا لیا تھا۔دیکھیں : ابن خلکان ۳ں ۳۸۱۔ لسان المیزان ۴؍۲۴۶۔ طبقات شافعیہ ۸؍۸۱۔] نے اہلِ کلام سے جو یہ بات نقل کی ہے کہ وہ ایک ایسے مفعول کے وجود کو ممکن مانتے ہیں جو کسی علت کے لئے معلول ہو ،ازلی ہو،اس کا ان میں سے کوئی بھی قائل نہیں بلکہ وہ اس بات پر متفق ہیں کہ ہر مفعول صرف اور صرف محدث (حادث)ہی ہوتا ہے۔
امام رازی اور اس کے امثال نے ابن سینا کی موافقت میں جو کچھ ذکر کیا ہے(یعنی یہ بات کہ ممکن جس کا وجود اور عدم دونوں ممکن ہو وہ کبھی قدیم اور ازلی بھی بنتا ہے)یہ اگلے پچھلے تمام عقلاء کے نزدیک قولِ باطل ہے۔ یہاں تک کہ ارسطور اور اس کے متقدمین اور متاخرین اتباع کے نزدیک بھی۔کیونکہ بے شک وہ باقی عقلاء کے ساتھ اس بات میں موافق ہیں کہ ہر ایسا ممکن جس میں وجود اور عدم دونوں کا امکان ہو وہ صرف اور صرف محدث ہی بن سکتا ہے جو کہ عدم کے بعد وجود میں آیا ہو۔اور ارسطو نے جب کہ یہ کہاکہ فلک قدیم ہے تو باوجود اس کے اس کو ایسا ممکن نہیں ٹھہرایا جس کا وجود اور عدم دونوں برابر ہوں یعنی اس میں دونوں کا امکان ہو۔
مقصود یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں مقدور اور مراد ہونے کا علم اُس کے حادث ہونے کو مستلزم ہے بلکہ اس کے مفعول ہونے کا علم ہی اس کے حادث ہونے کے علم کومستلزم ہے۔ کیونکہ صفتِ فعل ،خلق ،ابداع (از سر نوپیداکرنا)اور صنع اور اس جیسی دیگر صفات کا تصور تو مفعول کے حدوث کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی کہ کسی شے کے مفعول ہونے اوراس کے قدیم اور ازلی ہونے کے درمیان جمع بین النقیضین بھی ہے اور نفس الامری وجود میں کبھی بھی اس بات کا تصور نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسا فاعل پایا جائے جس کا کوئی مفعولِ معین ذات کے اعتبار سے اس کے ساتھ مقارن (متصل )ہو چاہے اسے علتِ فاعلیہ کہیں یا نہ کہیں لیکن شرط کا مشروط کے ساتھ مقارن ہونا تو سمجھ میں آتا ہے ۔